جدید غزل کا آئینہ
ڈاکٹر عادل حیات
ادب زمانی و مکانی روش و رفتار کا طابع ہوتا ہے۔اس پر اپنے عہد میں پروان چڑھنے والے تمام منفی و مثبت رجحان اور سماجی و سیاسی اور معاشی و اقتصادی حالات کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس مفروضے کی روشنی میں اردو کے تخلیقی ادب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ امیر خسرو سے ولی گجراتی تک دکن کے سماجی و سیاسی حالات کم و بیش یکساں رہے، اس لیے ادب میں عشق کے مجازی و حقیقی کا اظہار تخلیقی توانائی کے ساتھ ہوا۔ ولی گجراتی کے اثر سے جب شمالی ہند میں ادب بالخصوص غزل نے پرواز کرنا سیکھا تو اس زمانے کے مخصوص سماجی و سیاسی تصورات نے ایہام گوئی کے نظریے کو ہوا دی اور غزل دوہری زندگی جینے پر مجبور ہوگئی۔ زمانے کے ساتھ حالات و نظریات بھی بدلے، چنانچہ بہت جلد ایہام گوئی کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ مرزا مظہر جانِ جاناں، یقین اور شاہ حاتم نے ایہام گوئی کے رویے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ ’’تازہ گوئی‘‘ کی بنیاد رکھی۔ اسی تازہ گوئی کو میر و مرزا نے اپنی غزلوں میں برت کر بامِ عروج پر پہنچا دیا۔ ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، لیکن مکانی طور پر دونوں متضادمعاشرے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اسی استثنائے مکانی کے تحت میر کی تازہ گوئی داخلیت اور سودا کی تازہ گوئی خارجیت کہلائی۔ میر اپنے رنگ کے کم و بیش تمام امکانات کو تصرف میں لے آئے۔ چنانچہ آنے والے شعرا نے میر کی تقلید تو کی لیکن ان سے آگے نہ بڑھ سکے۔ سودا چونکہ اپنے رنگ کے تمام امکان کو تصرف میں نہ لاسکے، اس لیے ان کے رنگِ سخن میں بعد کے شعرا نے بھی گل بوٹے کھلائے۔ مصحفی نے میر و مرزا کے رنگ کو ملاکر اپنی غزلوں میں ایک نیا رنگ پیدا ضرور کیا لیکن ان کی اختراعی طبیعت نے انہیں اس راہ پر زیادہ دور تک بڑھنے نہیں دیا۔ جب دہلی کی بساط لٹ گئی اور زندگی کرنا محال ہوگیا تو شعرا نے رختِ سفر باندھا۔ اس زمانے میں لکھنو میں امن و امان تھا۔ معاشرے میں عیش و عشرت کے رنگ گھلے ہوئے تھے۔ چنانچہ دہلی کے مہاجر شعرا جنہوں نے وہاں جاکر بودوباش اخیتار کی وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے۔ اسی زمانے میں میر سوز نے اپنی غزل میں ’’ادا بندی‘‘ دوسرے لفظوں میں معاملہ بندی کے رجحان کوجنم دیا۔ جسے بعد میں جرأت نے شوخ و شنگ رنگ سے ہم آمیز کیا۔ چنانچہ یہ رنگ انہیں سے منسوب ہوکر رہ گیا۔ زمانہ بدلا تو پرانے تصورات بھی بدلے۔ اسی بدلے ہوئے حالات کے تحت ناسخ نے معنی بندی کے رجحان کو فروغ دینے کی جد و جہد شروع کی، جس میں وہ خاطر خواہ کامیاب تو رہے، لیکن وہ اس کے تمام امکانات کو اپنی غزلوں میں برت نہ سکے۔ بعد ازاں غالب اسی رنگِ سخن کو اپنا کر غزل کے سالارِ کارواں بن گئے۔
ہندوستان میں انگریزی سورج طلوع ہوا تو سماجی، سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالات بھی یکسر بدل گئے۔ ان بدلے ہوئے حالات میں حالی کی شخصیت ایک نقیب کی معلوم ہوتی ہے۔ جنہوں نے غزل کے فرسودہ و پامال مضامین پر تنقید کرتے ہوئے اس کا رشتہ مضامینِ تازہ سے جوڑنے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ غزل میں جدت پیدا کرنے، نئے اور اچھوتے مضامین شعر میں باندھنے کو کمال سمجھتے تھے۔حالی کے اصلاحی مشوروں سے متاثر ہوکر شعرا نے فرسودہ اور پامال روش کو ترک کردیا اور ایک ایسی روایت کی داغ بیل ڈالی جس پر چل کر نہ صرف خود ان کی غزل نے وقار حاصل کیا بلکہ نئی نسل کے شعرا کی رہنمائی بھی کی۔اس دور )جسے جدید دور سے بھی موسوم کیا جاتا ہے( کے شعرا جن میں حسرت، فانی، اصغر، فراق اور فیض نے غزل کو وسعت دی اور نئی سمتوں سے روشناس کرایا۔ اس لیے حسرت، فانی اصغر، جگر اور فراق کے اس دور کو غزل کے احیا کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ حکمراں، امرا و زمیندار طبقے کے ظلم و ستم نے کسانوں، مزدوروں اور چھوٹے موٹے کام کاج کرنے والے لوگوں کی زندگی میں زہر گھولنا شروع کیا تو اس کے خلاف شعرا و ادبا نے ایک تحریک شروع کی جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک چونکہ ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آئی تھی، جس کے تحت موضوع کا اظہار راست انداز میں کرنا ہی کامیابی کی علامت تھا۔اس لیے شعرا نے ایمائی اندازِ بیان کو چھوڑ کر غزل میں مضامین کا اظہار راست انداز میں کرنا شروع کیا۔ جس سے غزل کی روح متاثر ضرور ہوئی لیکن جلد ہی ایک نئی آواز حلقۂ اربابِ ذوق کی صورت میں بلند ہوئی۔ جس نے غزل کو اس کا کھویا ہوا وقار تو نہیں دلایا لیکن ایک نئے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ضرور کی۔ یہ وہی راستہ تھا جو آگے چل کر جدیدیت کے رجحان سے جاملتا ہے۔
آزادی کے بعد ہندوستانی سماج میں سائنسی اور صنعتی انقلاب رونما ہوا تو زندگی کرنے کے بہت سے مواقع بھی ہاتھ آئے۔ جن سے انسانی اطوار اور طرزِ فکر دونوں نمایاں تبدیلیوں سے ہمکنار ہوئے۔ اس بدلتے ہوئے منظرنامے نے انسانی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کرکے آسائش و آرام کی سہولت فراہم کی، لیکن اس کے ساتھ ہی زندگی بعض خدشات و خطرات سے بھی دوچار ہوئی اور اس کو ایسے کتنے ہی سہارے چھنتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر انسانی خلوص، تہذیبی اقدار بھی متزلزل ہوئیں۔ دولت و ہوس میں انسانی رشتے اور روابط بھی گم ہوتے چلے گئے۔ اس نئے تہذیبی ماحول میں انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ تنہائی کے اس احساس نے اس کے اندر خوف، بے اعتمادی، اداسی، تشکیک اور نارسائی جیسی کیفیات پیدا کردیں۔ جدید دور کے ان مسائل و میلانات کے اظہار کے لیے سابقہ ادبی نظریے اور شعری رجحانات ناکافی اور کبھی کبھی بے معنی نظر آنے لگے۔ چنانچہ ادب میں ایک نئے رجحان کا جنم ہوا۔ جسے ’’جدیدیت‘‘ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جدید شعرا نے بعض کلاسیکی اور مثبت ترقی پسندانہ موضوعات کے ساتھ ساتھ جدیدیت کے رجحان کے تحت معاشرے کی موجودہ صورتِ حال اور اس سے پیدا شدہ تنہائی، اجنبیت، بیچارگی، محرومی اور تشکیک جیسے مسائل و مراحل کو اپنا موضوع بنایا اور اپنے تخلیقی اظہار کی وساطت سے شاعروں نے خود کو ان تمام مسائل و میلانات سے بحسن و خوبی نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کیا۔
جدید غزل چونکہ اسی فریم ورک کا ایک حصہ ہے، اس لیے اُس کے موضوعات میں عام انسانی مسائل کے ساتھ سائنس اور ٹکنالوجی کی نئی نئی ایجادات اور صنعتی انقلاب سے پیدا شدہ نئے مسائل و معاملات بھی شامل ہیں اور ان کا اظہار براہِ راست نہ ہوکر احساسات و تجربات کی سطح پر یعنی داخلی حوالوں سے ہوتا ہے۔جدید غزل میں نئی فضا اور نیا ذائقہ یونہی پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے پسِ پشت تاریخی اور سیاسی محرکات بھی تھے، جن کی صورت واضح طور پر تقسیمِ ہند اور اس کے بعد کے حالات میں دکھائی دیتی ہے۔ اس پر میکانکی اور صنعتی انقلاب نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ انسان ذاتی مسائل و معاملات، خوف، تنہائی اور خود کلامی میں ایسا الجھا کہ انواح و اطراف پر دھند سی چھاگئی۔ تحفظِ ذات اور انفرادی تشخص نے انسانی زندگی اور تخلیقی اظہار میں غیر معمولی اہمیت حاصل کرلی۔ چنانچہ اس نئی صورتِ حال کے اثرات اس وقت کے شعر و ادب پر واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ حالی نے غزل میں در آنے والی خرابیوں کو آئینہ کیا تھا اور اس کی اصلاح کے لیے مشورے بھی دیے تھے لیکن یہ غلط فہمی نہ معلوم کہاں سے پیدا ہوگئی کہ حالی بطور صنف، غزل کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ حالی کا موقف غزل کی صنفی حیثیت کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اصلاح کے ذریعے اس کے موضوعی اور تخلیقی امکانات کو روشن کرنا اور ان کو وسعت سے ہمکنار کرنا تھا۔ اس رجحان نے آگے چل کر غزل کی مخالفت کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ جوش ملیح آبادی، عظمت اللہ خاں، نظم طباطبائی اور کلیم الدین احمد وغیرہ نے پر جوش انداز میں غزل کی مخالفت کی لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود غزل کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ اس نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ اس میں خیال کی وسعتیں بھی پیدا ہوئیں اور اظہار کی نئی نئی صورتیں بھی نکلیں۔ بہت سے شعرا جیسے اقبال، فانی، حسرت، جگر، اصغر، یگانہ، فراق اور فیض نے غزل میں نیا بانکپن پیدا کرکے اسے وسعت سے ہمکنار کیا۔
نئی غزل کے شعرا نے نہ صرف فراق، یگانہ اور بعض دیگر شعرا سے اکتساب کیا بلکہ غزل کی کلاسیکی روایت سے بھی خاظر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اس لیے ان کی غزلوں میں نئے مضامین و اسالیب کے ساتھ کلاسیکی رچاؤ نظر آیا ہے۔ نئی اور پرانی غزل کی مشترکہ خصوصیات میں غزل کی خارجی ہیئت اور داخلی آہنگ اہم ہے۔ غزل کی خارجی ہیئت میں چونکہ کوئی ردوبدل ممکن نہیں، اس لیے شعرا اپنے جذبات و خیالات کا اظہار اس کے مروجہ سانچے ہی میں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خارجی ہیئت کے اعتبار سے غزل کا رشتہ اپنی روایت سے مستحکم اور اٹوٹ ہوجاتا ہے۔ غزل کی داخلی ہیئت یا اندورونی آہنگ بھی اسے روایتی صنفِ سخن بناتا ہے۔ غزل کے مزاج کو سمجھے بغیر کسی بھی موضوع کا بیان ممکن نہیں۔ غزل کا مزاج چونکہ فرد کے داخلی تجربہ و احساس اور اظہار کے رمزیہ انداز سے تشکیل پاتا ہے، اس لیے کلاسیکی شعرا کے ساتھ جدید شعرا بھی اسی اصول پر کاربند نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی نئی غزل کا رشتہ اپنے ماضی سے استوار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
نئی اور کلاسیکی غزل میں مضامین اور طرزِ ادا کا جو فرق دکھائی دیتا ہے، وہ دراصل پرانی تہذیب و اقدار کے مسمار ہونے اور اس کی جگہ نئی تہذیب و اقدار کے تیزی کے ساتھ پاؤں پسارنے سے سامنے آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں تہذیبوں کے درمیان زمانی فرق ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل و معاملات میں بھی نمایاں فرق موجود تھا۔ جسے صنعتی اور میکانکی دور نے جنم دیا تھا اور جس نے انسانی زندگی اور اس کے معیار و معاملات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان بدلے ہوئے حالات میں ثقافتی انتشار، یکسوئی اور دل جمعی کے فقدان اور بے چہرگی کے احساس نے فرد کے اندر تنہائی، بیزاری اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کردی۔ نیا شاعر اپنی غزلوں میں انہیں مسائل کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے لہجے میں تلخی اور ترشی نہیں بلکہ خود کلامی اور آہستگی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی غزل کا بنیادی مسئلہ فرد کی تنہائی اور اس کا داخلی اضطراب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سائنس اور صنعتی ترقی نے جہاں انسانی زندگی میں آرام اور آسودگی کی کیفیت پیدا کی، وہیں اس نے انسانی قدروں کو پامال کرکے خود غرضی اور مطلب پرستی کو بڑھاوا بھی دیا۔ آرام و آسائش کی چاہت نے انسان کے شعور اور اس کے اجتماعی اندازِ فکر کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ انسانی اور سماجی رشتے کمزور ہوئے اور انسان کی تمام تگ و دو اس کی ذات تک محدود ہوکر رہ گئی۔ جس سے بے یقینی، تشکیک، تنہائی اور اداسی کے رویے نے جنم لیا۔ جدید غزل نے کسی نہ کسی شکل میں ان رویوں کی نمائندگی کی ہے۔ اسی احساس کو نئے شاعروں نے اپنے اشعار میں اس طرح پرویا ہے:
کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملوگے تپاک سے
یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو
بشیربدر
اس عہد سے وفا کا صلہ مرگِ رائیگاں
اس کی فضا میں ہر گھڑی کھونے کا رنگ ہے
منیرنیازی
کوئی ہے جو ہمیں دوچار پل کو اپنا لے
زبان سوکھ گئی یہ صدا لگاتے ہوئے
شہریار
جدید غزل میں تنہائی کا ذکر کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اسے اردو غزل کی روایت میں دور تک مختلف شکلوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ البتہ نئے اور پرانے زمانے میں تنہائی کی بعض قدریں مشترک ہونے کے باوجود اس کے اسباب مختلف ہیں۔ جدید دور کی برکتوں نے زندگی کو جتنی تیزی کے ساتھ جس طرح برق رفتار بنایا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان بلندیوں کو چھونے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہوس میں اپنی تہذیب و اقدار کو پامال کرتا چلا گیا۔ اس نئے دور کے انسان نے ترقی کے بہت سے مرحلے تو ضرور طے کئے لیکن اس کی آنکھوں سے منزل جیسے عنقا ہوگئی۔ یہی وہ حالات تھے، جنہوں نے انسان کے اندر خود پرستی کی کیفیت پیدا کردی اور وہ مسلسل ایک خاص جدوجہد میں سرگرداں رہنے لگا۔ اس کے نزدیک تمام رشتے ناتے معدوم ہوگئے اور وہ اپنائیت اور قربت کے احساس سے محروم ہوگیا۔ اسی خود پرستی نے فرار اور تنہائی کی کیفیت کو فروغ دیا اور یہی تنہائی جدید دور کے انسان کا مقدر ہوگئی نیز جدید شعرا کی غزل کا غالب رجحان بن گئی۔ چند اشعار بطورِ نمونہ پیش ہیں :
لمبی سڑک پہ دور تلک کوئی بھی نہ تھا
پلکیں جھپک رہا تھا دریچہ کھلا ہوا
محمد علوی
شاید کوئی چھپا ہوا سایہ نکل پڑے
اجڑے ہوئے بدن میں صدا تو لگائیے
عادل منصوری
تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو
تا حدِ نظر ایک بیابان سا کیوں ہے
شہر یار
رات ہمیں پھر تنہا پاکے جانے کیا کر بیٹھے
حسرت سے ہم دیکھ رہے ہیں دن کا سورج ڈھلتے
پرکاش فکری
جدید غزل میں تنہائی کا ذکر جس طرح اور جس پیمانے پر ہوا، اس سے اس لفظ نے ایک اہم موضوع کی حیثیت اختیار کرلی۔ اس لیے جدید غزل کے فکری نظام کی بات تنہائی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی۔ حالانکہ بہت سے ناقدین نے یہ بھی کہا کہ تنہائی جدید شاعر کا مقدر بن گئی ہے، انہیں اپنی تنہائی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے وہ تنہائی کے ذکر کے علاوہ اپنی غزلوں میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے۔میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں ایک خاص طرح کے تعصب کے تحت کی گئیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کرچکا ہوں کہ شعر و ادب میں کسی بھی غالب رجحان کے اسباب کی تلاش اس وقت کی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مخصوص صورتِ حال اور انسانی رویوں میں کرنا چاہیے۔ غزل میں تنہائی کے جواز کو بھی جدید دور کے میکانکی اور شہری زندگی میں تلاش کرنا ہوگا۔نیا شاعر تنہائی کے جس کرب سے گزر رہا تھا، اس میں عدم تحفظ کا احساس بھی غالب تھا۔ اس لیے وہ اپنی ذات سے باہر ہر چیز کو تشکیک کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہوگیا تھا، جیسے ہر چیز اس کی شخصیت کی شکست و ریخت کے در پے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جدید غزل میں تنہائی کے احساس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات کے طور پر علاحدگی پسندی، بیگانگی، بے چہرگی، لاسمتیت اور تشکیک جیسے رویوں کی عکاسی بھی کی گئی:
ہر ایک سمت ہے آسیب مرگ چھایا ہوا
میں اپنے جسم کو لے کر کہاں نکل جاؤں
کمار پاشی
کرنا پڑے گا اپنے ہی سائے میں اب قیام
چاروں طرف ہے دھوپ کا صحرا بچھا ہوا
وزیر آغا
جدید غزل میں صرف اور صرف تنہائی اور اس کے متعلقات کی ترجمانی ہی نہیں ہوئی بلکہ جدید شعرا نے زندگی کا گہرائی کے ساتھ وسیع مطالعہ کیا اور اس کے مظاہر و میلانات سے بھی دلچسپی دکھائی۔ اس لیے جدید غزل میں زندگی اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اس میں سیاسی صورتِ حال اور سماجی مسائل بھی ہیں۔ بین الاقوامی و مقامی اور روز مرہ کے پیچیدہ واقعات کی عکاسی بھی ہوئی ہے۔ جدید غزل میں تقسیمِ ہند کے بعد کے حالات بھی موضوع بنے ہیں اور اس میں ہجرت سے پیدا شدہ مسائل کا بیان بھی ہوا ہے۔
اڑ گئے شاخوں سے یہ کہہ کر طیور
اس گلستاں کی ہوا میں زہر ہے
ناصرکاظمی
زمینِ سرد سے اک گرم آب جو نکلی
پہاڑ کاٹ کے دریا کا راستہ نکلا
باقرمہدی
جدید غزل قنوطی، رجائی، اشتراکی، سیاسی، ہوسناکی یا معاملہ بندی کے ذیل میں نہیں آتی، البتہ یہ سارے رجحانات اس میں تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ جدید غزل کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی حسنِ خیال اور حسنِ تاثیر کی امین ہے، اور روایت کی مثبت، بامعنی اور فنی اقدار سے اس کا رشتہ تخلیقی سطح پر ہمیشہ استوار رہا ہے۔ البتہ بعض شعرا نے جن میں ظفر اقبال، بشیر بدر اور محمد علوی پیش پیش رہے، انتہا پسندی سے کام لیتے ہوئے غزل کے مروجہ سانچے میں ’’جذباتی برہنہ گفتاری‘‘ کو بھی شامل کرلیا۔ جسے بعد میں اینٹی غزل‘‘ کا نام دیا گیا۔ بعض جدید شعرا نے کچھ نیا کرنے کی کوشش میں غزل کی روایت سے انحراف کا رویہ اپناتے ہوئے غزل کی صورت کو مسخ کیا۔ حالانکہ غزل کی اس نئی صورت میں نہ تو اس کا باطنی آہنگ باقی رہا اور نہ ہی تسلسل۔ اس میں غزل کا مخصوص رمزیاتی و ایمائی طریقِ کار بھی عنقا ہوگیا۔ اینٹی غزل میں کوئی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو وہ جذباتی برہنہ گفتاری ہے۔ کلاسیکی دور کے شعرا مثلاً انشا اور ان کے بعض ہم عصروں کے یہاں بھی اس طرح کا رجحان ملتا ہے۔ جس نے بعد میں خارجیت کا رنگ اختیار کر لیا اور اردو غزل کو صرف لفظی شعبدہ بازی بنا کر رکھ دیا تھا۔
جدید دور کے بعض شعرا کے نزدیک غزل کی ہیئت جامد تھی، جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ غزل کے عام تصورات و موضوعات کو تبدیل کیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا تصور قائم کیا جائے۔ شمس الرحمن فاروقی کی رائے میں غزل کی روایت انسانی ذہن میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ لاکھ چاہنے کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے محمد علوی اور ظفر اقبال کو اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے اینٹی غزل کا سہارا لینا پڑا۔ ہمارا خیال ہے کہ کچھ منفرد اور نیا کرنے کے لیے کرتب بازیوں سے زیادہ تخلیقی ذہانت اور زرخیزیِ خیال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن شمس الرحمن فاروقی جیسے ناقدین کی بے جا وکالت نے ایسے شعرا کے حوصلوں کو بڑھایا اور ادب میں خلفشار کی فضا پیدا کی۔ کیا ظفر اقبال اور محمد علوی اپنے اس تجربے کی بنیاد پر زندہ ہیں یا ان کی انفرادی شناخت (اگر کوئی ہے) کی کوئی اور وجہ ہے؟ دوسرے یہ کہ مذکورہ شعرا کے یہ نام نہاد تجربات کسی کڑوی کسیلی یاد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ جدید شعرا میں کچھ شاعر ایسے بھی تھے جو ٹیڈی تہذیب سے متاثر تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک قدم اور آگے رکھتے ہوئے غزل میں ایک تجربہ ’’ٹیڈی غزل‘‘ کے نام سے بھی کیا، جس کی تصویر کشی کرتے ہوئے اختر احسن نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا:
ہے بدی پاؤں سے سر تک اچھی
تنگ پتلون میں ٹیڈی لڑکی
اور جس کی تقلید بشیر بدر نے اس طرح سے کی:
ٹیڈی تہذیب، ٹیڈی فکر و نظر
ٹیڈی غزلیں سنا رہے ہیں ہم
جدید شعرا کی ان بے اعتدالیوں کو جیسا کہ پیشتر کہا گیا کچھ ناقدین کی پشت پناہی حاصل ضرور ہوئی لیکن بیشتر ناقدین نے ان منفرد رجحانات کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جدید شعرا نے منفی رجحانات کے تحت روایت سے انحراف تو کیا ہی ساتھ ہی اپنی غزلوں میں معشوق کے لیے موئنث ضمیر و افعال کا استعمال شروع کیا۔ جس کی تقلید کرتے ہوئے بعض شاعرات نے بھی اپنی غزل کے محبوب کے لیے مذکر ضمیر و افعال کا استعمال ضروری سمجھا۔ مثال کے طور پرچند اشعار دیکھیں :
میں چھپانا چاہتا ہوں برہنہ خواہش
وہ سمجھتی ہے کہ شرمیلا ہوں میں
انور شعور
مجھ کو ترے فراق کا احساس ہے مگر
میں تیرے پاس آنہیں سکتی ہوں، کیا کروں
نجمہ تصدق
اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معتبر شعرا نے غزل کی اشاریت و ایمائیت کے پردے میں جدید حسیت اور نئے مضامین کی ترجمانی بخوبی کی ہے، لیکن بعض شعرا فیشن پرستی کے طور پر حدود سے تجاوز کرتے ہوئے جدید حسیت اور نئے مضامین کے نام پر اسما و اشیا کی فہرست سازی کرنے لگے۔ نئی غزل میں روزمرہ کے ایسے واقعات و حادثات کا بیان بھی کیا جانے لگا، جن میں شاعر کے تجربے، مشاہدے اور شعوری سطح سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا اور ان سے قارئین کے جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان مضامین کو پیش کرنے کے سلسلے میں شعرا نے غزل کی فنی و فکری خصوصیات کو بھی نظر انداز کردیا تھا۔ اس لیے ایسے اشعار سپاٹ اور بے رس ہوکر رہ گئے، جن کا تعلق امورِ ذہنیہ سے قائم ہوسکا اور نہ ہی وارداتِ قلبیہ سے۔ اس طرح کے چند اشعار بطور مثال پیش ہیں :
گھر والی کے واسطے بچی نہ پیالی چائے کی
کتے، بلی آن کر کھاگئے کیک مٹھائیاں
ظفراقبال
بتی بجھا کے ہیرو ہیروئین لپٹ گئے
قصہ بہت ہی پھر تو مزیدار ہوگیا
محمد علوی
آکے اب جنگل میں یہ عقدہ کھلا
بھیڑیے پڑھتے نہیں ہیں فلسفہ
سلیم احمد
بیٹ کرجاتی ہیں چیڑیاں فرش پر
عظمتِ آدم کا آئینہ ہوں میں
انورشعور
ان کے علاوہ جدید غزل میں جنسی بے اعتدالیوں کا اظہار بھی کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنسی جذبات کے متعلق خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کو چھپانے یا دبانے سے بعض اوقات نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان غیر فطری اعمال کا مرتکب ہوجاتا ہے۔ اردو غزل کی روایت میں جنس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوا ہے لیکن جدید شعرا نے جنس کے اعتدالی رویوں کو چھوڑ کر اس کی پیشکش میں جس ابتذال اور عریانیت کو روا رکھا وہ ہماری تہذیبی روایت سے ہم آہنگ نہیں۔
زندہ اور متحرک صنف کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے تخلیقی عہد کے ذوق اور مزاج سے بیگانہ نہیں ہوتی بلکہ بدلتے ہوئے وقت اور حالات کا پھر پور ساتھ دیتی ہے۔ اردو غزل کی یہ خوبی ہے کہ اس نے بھی اپنے تخلیقی عہد کے ذوق اور مزاج سے بیگانگی نہیں برتی اور بدلتے ہوئے وقت اور حالات کا موضوع کے ساتھ ساتھ اسلوب کی سطح پر بھی ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کی مقبولیت ہر زمانے اور ہر عہد میں یکساں طور پر قائم رہی۔ آزادی کے بعد ہند و پاک میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کے اثرات غزل کے موضوعات کے ساتھ ہی اس کی لفظیات پر بھی پڑے۔ جدید غزل چونکہ جدید حالات اور گردوپیش کے تجربوں سے دوچار ہوکر لکھی گئی، اس لیے غزل گو نے عام زندگی اور عام انسانی تجربات کو زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ جدید غزل میں لب و لہجے کی سطح پر ہونے والی تبدیلوں کو وقت اور حالات کے تقاضے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جدید غزل کی لفظیات اور تلمیحات و استعارات نئے ماحول اور معاشرے نیز انسانی تجربات و احساسات و تجربات کے عکاس ہیں، چنانچہ جدید غزل کا شاعر الفاظ کو محض سطحی طور پر استعمال کرنے کے بجائے ان کا تخلیقی استعمال گہرائی و گیرائی کے ساتھ کرنے لگا۔ اس سلسلے میں بعض ایسے الفاظ جو شاعر کے احساسات و تجربات کی ترجمانی نہیں کرسکتے تھے، انہیں ترک بھی کیا گیا اور بعض نئے الفاظ تراشے بھی گئے اور بہت سے الفاظ جو پہلے کسی اور معنی میں استعمال کئے جاتے تھے، انہیں نئے معنی کا جامہ پہنایا گیا۔ اس لیے جدید اور پس جدید غزل کی لفظیات میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
جدید غزل میں الفاظ کی اندرونی تفہیم کا دھیرے دھیرے بدلنا، اس میں نئے الفاظ کا داخل ہوکر نئی اشاریت اور نئی معنویت سے ہمکنار ہونا، جدید شاعروں کی جدت پسندی کا دوسرا رخ تھا۔ نیا شاعر اپنی غزلوں میں احساسات و تجربات کا اظہار جس طرح راست اور بالواسطہ انداز میں کررہا تھا، اس کا اثر غزل کی زبان پر بھی پڑنا لازمی تھا۔ وہ غزل کی مروجہ زبان سے دور، عام محاوروں سے ہٹی ہوئی اور کاروباری زندگی سے بہت قریب ہے۔ یہ زبان چونکہ زمانے کے تجربات و احساسات کے اظہار کے طورپر برتی گئی، اس لیے جدید غزل کے لب و لہجے میں غیر رومانی پن اور ناہمواری کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ چنانچہ جدید غزل کی پہچان غیر شاعرانہ، سخت اور مجرد الفاظ، کھردرا اندازِ بیان اور اکھڑے اکھڑے لب و لہجے کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔
نیا شاعر چونکہ الفاظ سے زیادہ اپنے موضوع کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے پر تکلف، پر تصنع اور پرشکوہ انداز نہیں بلکہ سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ اس کی بات آسانی کے ساتھ ترسیل کے مراحل سے گزر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ کی بالادستی اس پر نہیں ہوتی۔ زبان کی حیثیت تو ایک ٹول(Tool) کی ہے۔ جس کوہرایک استعمال کرنے والا اپنی طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ ایک زرخیز ذہن کا مالک ہے اور لفظ کے تخلیقی امکانات سے واقف ہے تو وہ اپنے تخلیقی تجربے کے تقاضے کے مطابق زبان کا استعمال کرے گا۔ بعض ناقدین کے خیال میں شاعر کی تخلیقی فکر اپنے اظہار کے سانچے کو خود واضح کرتی ہے، جو کہ زمانے کی عام روش کے ساتھ سیاسی، سماجی اور تہذیبی طور پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے طابع ہوتی ہے۔ غزل کا رویتی اسلوب چونکہ نئے موضوعات کی پیشکش کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے نئے تجربات خود ہی جدید شاعر کے احساسات کا حصہ بن کر نئے الفاظ کے متلاشی ہوئے لیکن شعرا نے ان الفاظ کو اکہرے معنی میں نہیں برتا بلکہ ان کے تخلیقی استعمال میں رمز و ایما کو خاص اہمیت دی گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے تخلیقی استعمال نے علامت نگاری اور پیکر تراشی کے رجحان کو فروغ دیا، البتہ یہ بات الگ ہے کہ کلاسیکی غزل کی نمایاں خصوصیت بھی اس کا ایمائی انداز ہی تھا، جس سے غزل کے اشعار میں تہہ داری پیدا ہوتی ہے۔ ترقی پسندوں نے جب اسے خیر باد کہا تو غزل کا اسلوب سپاٹ اور بے رس ہوکر رہ گیا۔ روایتی غزل کی لفظیات، تشبیہات، استعارات اور علامتوں پر فارسی کے اثرات تھے، جس میں بڑی حد تک ایرانی ماحول اور وہاں کی مٹی کی بوباس تھی۔ جدید شعرا نے اپنے جذبہ و خیال کے لیے نہ صرف نئی لفظیات کی دریافت کی بلکہ نئی نئی اور ایسی تشبیہات و استعارات اور علامتوں سے اپنی غزلوں کو آراستہ کیا، جن میں اپنی مٹی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ چند اشعار پیش ہیں، جن سے نئی غزل میں علامتوں کی مختلف صورتوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ان علامتوں میں گردوپیش اور ماحول کی خوشبو کو محسوس کیا جاسکتا ہے:
ریت پر ماہیِ بے آپ نے پھیلائے تھے جال
صید امواجِ سراب ایک مچھیرا نکلا
وحید اختر
ساری آوازوں کو سنّاٹے نگل جائیں گے
کب سے رہ رہ کے یہی خوف ستاتا ہے مجھے
شہر یار
میں ایک ذرّہ میری حیثیت ہی کیا ہے
ہوا کے ساتھ ہوں، اڑتے ہوئے غبار میں ہوں
عادل منصوری
اب بھی قدموں کے نشاں ملتے ہیں
گاؤں سے دور پرے جنگل میں
محمد علوی
زبان کے تخلیقی استعمال نے نئی غزل میں پیکر تراشی کے عمل کو بھی مقبول بنایا۔ پیکر تراشی کا یہ عمل کلاسیکی دور کی غزلوں کے ساتھ ترقی پسندوں کے یہاں بھی بکثرت ملتا ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے تجربہ و احساس کو زیادہ اثر انگیز اور بھر پور طریقے سے ادا کرسکتا ہے۔ جس طرح جدید شعرا کے یہاں نئے نئے تجربوں کی روشنی میں لفظوں کی تراش خراش سے نئی نئی اصطلاحیں، نئی نئی تشبیہیں اور استعارے وضع ہوتے ہیں، اس طرح تخلیقی تجربے کی پیچیدگی اور تنوع کی عکاسی کے لیے شعری پیکر بھی خلق ہوتے ہیں۔ جدید غزل کو پڑھتے ہوئے نئے احساس کی ایک دنیا آباد ہوجاتی ہے اور ذہن میں مختلف کیفیات کے نقوش ابھرنے لگتے ہیں۔ اس طرح نہایت متنوع پیکر ہمارے پردۂ فکر پر ابھر آتے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ ان پیکروں میں بصری پیکروں کی بہتات ہے۔ اس حوالے سے چند شعر دیکھیں :
اب کہ ایسی پتجھڑ آئی سوکھ گئی ہے ڈالی ڈالی
ایسے ڈھنگ سے کوئی پودا کب پوشاک بدلتا تھا
خلیل الرحمن اعظمی
راہ میں راکھ ہوگئیں دھوپ کی پتیاں ظفر
آنکھ بکھر بکھر گئی اپنی ہی آب و تاب سے
ظفراقبال
شکیب دیپ سے لہرا رہے ہیں پلکوں پر
دیارِ چشم میں کیا آج رت جگا ہے کوئی
شکیب جلالی
جنوری کی سردیوں میں ایک آتش داں کے پاس
گھنٹوں تنہا بیٹھنا، بجھتے شرارے دیکھنا
سلیم احمد
جدید غزل میں ہیئت کے تجربوں کی کئی صورتیں سامنے آئیں۔ ان سے متعلق کا فی بحث و مباحثے بھی ہوتے رہے۔ بسا اوقات یہ بحثیں غلط فہمی پر بھی مبنی رہیں۔ عام طور پر غزل کی طاہری شکل و صورت کو ہی اس کی ہیئت سمجھ لیا گیا اور اس کی باطنی حیثیت فراموش کردی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی صنف کی تشکیل میں جتناتعاون اس کی ظاہری شکل و صورت کا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے باطن یعنی فکرومواد کا بھی ہوتا ہے۔ غزل کی ہیئت میں اس کا ظاہری آہنگ، الفاظ کی بندش، احساس کی شدت، مخصوص بحر، قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہر شعر کا معنی کے اعتبار سے ایک مکمل اکائی کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے چھیڑ چھاڑ کا مطلب اس کی صنفی خصوصیات سے انکار ہے۔ غزل کے سلسلے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ہیئت میں کوئی تجربہ ممکن نہیں تو اس سے مراد در اصل اس کی خارجی ہیئت ہوتی ہے۔ غزل کی ہیئت میں چونکہ اس کا داخلی نظام یعنی معنی و مواد بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ جس میں حسن و عشق کی داستان کے ساتھ ابتدائی زمانے ہی سے دنیا جہان کے دوسرے مضامین شعرا نے تجربہ و احساس کے طورپر پیش کئے ہیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ہیئت میں تجربے ہوتے رہے ہیں تو اس سے مراد غزل کی خارجی ہیئت نہیں بلکہ اس کی داخلی ہیئت ہوتی ہے۔ ہمارے بعض ناقدین کا ذہن اس سلسلے میں صاف نہیں ہے۔ وہ موضوع، اسلوب اور ڈکشن کے حوالے سے غزل میں ہونے والے تجربے کو ہیئتی تجربہ نہیں مانتے۔ اس کے باوجود بعض شعرا نے اپنی اختراعی طبیعت کے باعث غزل کی خارجی ہیئت میں بھی تجربے کئے ہیں لیکن یہ عمل تجربہ برائے تجربہ ہی ثابت ہوا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ غزل کی خارجی ہیئت سے چھیڑ چھاڑ کا مطلب اس کی صنفی خصوصیت سے انکار ہے۔ غزل کی خارجی ہیئت میں جو تجربے ہوئے، انہیں آزاد غزل، غزلیہ، اور غزل نما جیسے ناموں سے پکارا گیا، لیکن یہ تجربے خاص و عام میں مقبولیت حاصل نہ کرسکے۔
جدید غزل میں سائنسی اور صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے مسائل و میلانات کا تخلیقی اظہار شعرا نے اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہے۔ اس لیے جدید غزل میں تنہائی اور اس کے متعلقات کے طور پر خوف، بے اعتمادی، نارسائی، اداسی اور تشکیک وغیرہ کے تخلیقی اظہار کو حاوی رویے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں جدید غزل حسن و عشق کے موضوعات سے بھی آراستہ ہے لیکن ان تمام موضوعات کا اظہار ترقی پسندوں کی طرح راست انداز میں نہیں بلکہ نئی اور پرانی علامتوں، استعاروں، تشبیہوں اور بعض دوسری صنعتوں کے ذریعے تخلیقی طور پر ہوا ہے۔ جدید غزل گو شعرا نے رسمی مضمون آفرینی، فرسودہ طرزِ بیان اور تصنع کو خیر باد کہا اور فطری، غیر رسمی اور انفرادی شعری اظہار کی راہیں ہموار کیں۔ اس لیے جدید غزل میں زبان و بیان کا نیا ذائقہ بھی ہے اور اس کا رشتہ روایت سے بھی استوار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جدید شعرا کے یہاں بعض کلاسیکی شعرا کی بازیافت کا عمل بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ابنِ انشا اور فراق کی غزل میر کے لہجے کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس کے برعکس ظفر اقبال، حسن نعیم اور نشتر خانقاہی کی شعری کائنات میں غالب کا رنگ بکھرا ہوا ہے۔ بعض جدید شعرا نے غزل کی مروجہ ہیئت کو برقرار رکھتے ہوئے اینٹی اور ٹیڈی غزل جیسے تجربات بھی کئے ہیں اور اس کے اوزان میں کمی بیشی کرکے آزاد غزل کہنے کی کوشش بھی کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایسے تمام تجربات محض تجربات کی حد تک ہی محدود ہوکر رہ گئے۔ غزل کا جو رنگ روپ پہلے تھا وہ فکری و فنی سطح پر تغیرات کے بعض مرحلے طے کرتا ہوا موجودہ عہد میں بھی اسی طرح برقرار ہے۔

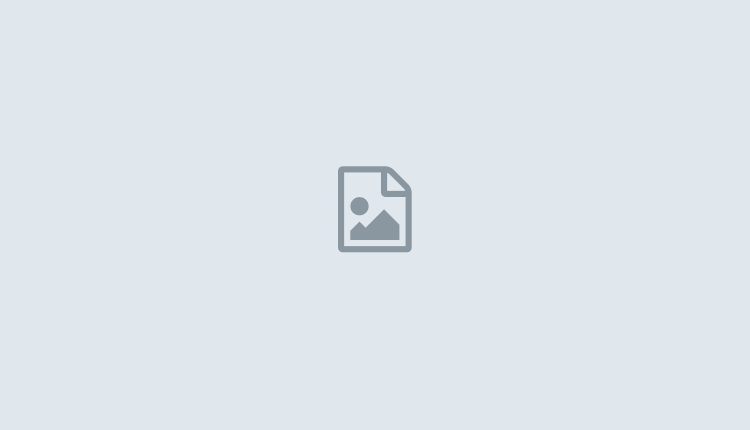
تبصرے بند ہیں۔