ذکیہ مشہدی
نانی کا نانہال
گرچہ وہ خود عرصہ پہلے نانی بن چکی تھی اور عرصۂ دراز کے بعد اپنے نانہالی گائوں آئی تھی لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا۔ اگر بدلا بھی تھا تو بس اتنا ہی کہ نظر میں نہ آئے۔ کوئی بتائے تبھی محسوس ہو۔
ٹرین نے حسب معمول اس اونگھتے اداس اسٹیشن پر اتارا۔ وہاں سے ایک بس لینی پڑی جس کی چولیں ہلی ہوئی تھیں۔ اس نے جہاں لاکر چھوڑا وہاں کے بعد سڑک نہیں تھی۔ اور نانہال ابھی چار پانچ کلو میٹر آگے تھا۔ گائوں کے رشتے سے ماما کہلانے والا رام سَگن ٹم ٹم لے کر آیا ہوا تھا۔ بوڑھا پھوس دیسی ہی گھوڑی۔ گائوں کے لوگ تو یہاں سے پیدل رپٹ دیا کرتے تھے۔ ٹم ٹم شاذ و نادر چلتی۔ بیل گاڑیاں تقریباً ناپید تھیں۔
زرین نے اسے پہچان لیا۔ اس نے بھی۔ چندھی بُوا کے ہاتھ کا سہارا لے کر زرین بدقت تمام ٹم ٹم میں سوار ہوئی۔
’’مالک گیہوں چھِٹوا رہے تھے۔ ’’رام سگن نے انگوچھے سے چہرہ پونچھا پھر کودتے ہوئے ٹم ٹم پر سوار ہوکر بتایا۔ ’’بس کھڑے کھڑے گِر گئے۔ کبھی بیمار نہیں پڑے تھے۔ سردی کھانسی ہوئی تو بس تلسی کا کاڑھا پی لیا۔ گائوں میں کوئی زیادہ بیمار نہیں پڑتا۔ جانتا ہے پڑے گا تو دوا دارو نہیں ملے گی۔ پھر اس نے قدرے توقف کے بعد کہا ’’ہمارے جوان بھتیجے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ لاد کر سنٹر لے گئے۔ جانے میں ہی دو گھنٹے لگ گئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بَس لے کر انو منڈل گئے۔ ہسپتال میں پڑا رہا۔ علاج شروع ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ‘‘
’’تب؟ ‘‘ چندھی بُوا نے بلا وجہ ہی سوال کر ڈالا ورنہ بات تو عیاں تھی۔
’’تب کیا۔ چل بسا۔ ایک ہی لڑکا تھا۔‘‘
رام سگن ہمیشہ سے بہت بولتا تھا۔ لیکن اس وقت تو وہ اپنا دُکھ بانٹ رہا تھا۔ زرین کی آنکھیں بھر آئیں۔ بہت دن سے سوچتی تھی کہ ایک بار گائوں آکر ماموں سے مل لے۔ وہ اس سے بس کوئی چار ایک برس بڑے تھے۔ یہاں آتی تھی تو خالہ ماموں اس کے ساتھ مل کر بھائی بہنوں کی طرح کھیلا کرتے تھے۔ پہلے شادیاں اتنی کم عمری میں ہوتی تھیں کہ کئی کنبوں میں تو ماں بیٹی کے یہاں آگے پیچھے بچے پیدا ہوتے رہتے تھے۔ لوگوں کو نہ اس پر حیرت ہوتی تھی نہ اسے مضحکہ خیز سمجھا جاتا تھا۔
اداسی کے باوجود دل میں کچھ یادوں نے گد گدی کی۔
نو عمری کے زمانے میں وہ یہاں ایک شادی میں آئی تھی۔ دلہن کے چھوٹے بھائی کی ختنہ کی رسم بھی اسی شادی میں نمٹائی جا رہی تھی پھر بھی دلہن کی والدہ کہیں نظر نہیں آرہی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا وہ تو ’’سوری‘‘٭ میں ہیں۔ بیٹا ہوا ہے۔ جو مہمان شادی میں آئے تھے وہ نو مولود کا منہ دیکھ کر کوئی پانچ روپے، کوئی گیارہ روپے سرہانے رکھ رہے تھے۔ مراثنوں نے بیاہ کے گیتوں کے ساتھ زچہ گیریاں بھی گائیں۔ دلہن کی اماں کچھ حیا کچھ فخر و انبساط سے سرخ ہوگئیں۔ چار بیٹیوں کے بعد یہ ان کا دوسرا بیٹا تھا۔
ٹم ٹم ہچکولے لے رہی تھی۔
’’ٹھیک سے رام سگن۔ بی بی کی بوڑھی ہڈیاں ہیں۔ ‘‘ چندھی بُوا نے ٹوکا۔
ارے تو ہماری کون سی نئی ہیں۔ اس نے چابک لہرا کر گھوڑی کو دھمکایا اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں شروع کردیں۔
’’پچھلے چناؤ میں پکا وعدہ کیا تھا کہ یہاں سڑک بن جائے گی۔ سڑک بن جاتی تو آٹو چلنے لگتا۔ لڑکوں کا کیا۔ پیدل چل کے آرام سے بس اڈے آجاتے ہیں۔ عورتیں ہوئیں، ہم جیسے بڈھے ہوئے، ارے ہماری ہڈیاں پرانی سہی اب بھی کچھ مضبوط ہیں۔ دھکے سہہ لیتے ہیں۔ بیل
زچہ خانہ جو گو میں ہی ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔
گاڑی کا رواج نہیں رہا۔ گائوں میں ایک آدھ ٹم ٹم ہے۔ نہ ہوتی تو آپ لوگوں کو بھی پیدل چلنا پڑتا۔ ‘‘
’’تو نہ آتے۔ کیا کرنے آتے تب۔ ’’چُندھی بوا کی زبان بھی پٹا پٹ چلتی تھی۔
’’نہ کیسے آتیں بی بی۔ مالک کی بڑی لاڈلی تھیں۔ ایک توپندرہئیوں نہیں آئیں۔ شہر کی ہوا لگ گئی ہے ہماری بی بی کو۔ ٹم ٹم نہ ہوتی تو ہم ڈولی لے کے آتے۔ مالک کے گھر میں ایک پرانی ڈولی پڑی ہے۔ کہار جُٹا لیتے۔ بھیا کیوں نہیں آئے؟ ‘‘ اسی سانس میں اس نے زرین کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔
’’بھیا کی دلہن انہیں اڑا لے گئیں سات سمندر پار۔ چھاپ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ‘‘
چندھی بُوا جو منہ میں آئے بول دینے کے لئے مشہور تھیں۔ آگا پیچھا کچھ نہ دیکھتیں۔ زرین کا کسی بھی قسم کا احتجاج بیکار ہوتا اس لئے وہ خاموش رہی۔
’’بڑے آدمی چھوٹے آدمی سب کی ایک ہی کہانی ہے۔‘‘ رام سگن نے اداس لہجے میں بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا۔
’’تمہاری بہو بھی اڑا لے گئی کیا تمہارے بیٹے کو؟‘‘
اب کی زرین سے نہ رہا گیا۔ ’’چپ بھی رہا کرو کبھی۔ ‘‘ اس نے سخت لہجے میں بوا کو تنبیہہ کی —
ماموں کے گھر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ویسا ہی تھا۔ نیم پختہ، مٹی سے لیپا پوتا۔ حاطے میں چھپرکے نیچے دو گائیں جگالی کر رہی تھیں۔ بس ہاں ماموں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اداسی اور ویرانی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ یا شاید زرین کو ہی ایسا لگ رہا تھا کیوں کہ مشترکہ خاندان ہونے کے سبب لوگ تو بہتیرے تھے۔ جوان، بچے، ادھیڑ۔ اور بوڑھی ممانی بھی۔ بے حد بوڑھی، بہری بھنڈ۔ کھٹولی میں سکڑی سمٹی پڑی رہتیں اور خود ہی اپنی مکھیاں جھلا کرتیں۔ بس اتنے ہی ہاتھ پائوں چلرہے تھے۔ زرین کو انہوں نے نام سے پہچانا۔ نا قابل فہم الفاظ میں دعائیں دیں۔ مرحوم شوہر کو پکارا، فلانے کے ابا، آکے مل لو۔ بھانجی آئی ہے۔ زرین کے گلے میں کچھ پھنسنے لگا۔
دونوں ماموں زاد ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکے تھے اور عمر بڑھنے پر زیادہ کم سخن، زیادہ مُلّاٹے ہو گئے تھے۔ ڈاڑھیاں سینے تک اور پاجامے ٹخنوں سے اوپر۔ بیوی بچوں پر شیر کی نظر۔ ویسے دل اور معاملات کے صاف تھے۔ مزاج میں مروت اور رشتوں کی پاسداری تھی۔ غمی کا موقعہ تھا پھر بھی زرین کی آمد سے سب خوش ہوگئے۔ اس کے لئے مرغ ذبح کیا، پلائو پکایا۔ الگ بٹھا کر کھِلایا اس لئے کہ یہ نعمتیں سب کے لئے وافر مقدار میں نہیں تھیں۔ دوسرے و ہ سب اب بھی دھواں دیتے، کچے فرش والے باورچی خانے میں پیڑھیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔
نانا اپنی زمین جائداد میں اضافہ نہیں کرسکے تھے۔ الٹا اس میں کمی آئی تھی۔ بیٹوں کو مدرسے میں بڑھایا اور باغبانی اور کسانی میں ہی لگائے رکھا۔ کیڑالعیال بھی تھے۔ یہی سب دیکھ کر زرین کی ماں اپنے مائکے کی جائیداد سے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوگئی تھیں۔ جب ان کی ماں کے زیور تقسیم ہوئے تو ان میں بھی اپنا حصہ نہیں لیا۔ شادی کے وقت ہی انہیں خاصہ سونا مل گیا تھا۔
’’بجلی ابھی تک نہیں آئی؟‘‘ کھانا کھاتے ہوئے زریں نے پوچھا۔
’’تار کھنچ رہے ہیں۔ کھمبے عرصہ ہوا گاڑے جا چکے۔ کبھی لائن بھی آ جائے گی۔ ‘‘ بھاوج پنکھیاسے مکھیاں اڑا رہی تھیں۔ انہوں نے جواب دیا۔
’’جہاں لائن آگئی ہے وہاں رہتی کب ہے؟‘‘ بھتیجے کا کمنٹ تھا۔
لائن سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ بیت الخلا بن جاتے۔ زرین نے سوچا۔ اس نے آتے ہی بیت الخلا کے بارے میں پوچھا تھا۔
’’زیادہ تر لوگ اب بھی کھیت جاتے ہیں۔
’’ہمارے یہاں کچھ انتظام ہوگیا ہے۔ جائیے ہو آئیے۔ اے فلا نے، ذرا پھوپی کو ’باہر‘ لے جائو۔‘‘ ماموں زاد بھاوج نے کہا۔
نہیں نہیں۔ ذرا رک کے۔ اس نے ہڑ بڑا کر یوں بے ساختہ کہا جیسے اسے امرودوں کے باغ میں جانے کو کہہ دیا گیا ہو۔ یہ امرودوں کے باغ کا قصہ زرین کی سائیکی کا حصہ تھا جو اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔
امرودوں کا باغ
زرین کی دادی زرین کی ماں کو اکثر اس کا طعنہ دیا کرتی تھیں۔
زرین کی ماں کی شادی سن چالیس میں ہوئی تھی۔ اس وقت پورے گائوں میں چودھریوں کو چھوڑ کر کسی کے یہاں بیت الخلا نہیں تھا۔ وہ بھی نہایت بھدّا سا۔ باقی کیا غریب، کیا کھاتے پیتے (اور گائوں میں کھاتے پینے خاندان معدودے چند ہی تھے) سب کے سب کھیت جاتے تھے یا ندی کنارے سر کنڈوں کے جھاڑ کے پیچھے۔ اور ہاں بسواڑی بھی تھی۔ لوگ منہ اندھیرے جاتے۔ خاص طور پر عورتیں تاروں کی چھائوں میں نکل لیتیں۔ شہر سے آنے والی بارات کو سارا دن، ساری رات ٹھہر کر کہیں دوسرے دن سہ پہر کو رخصت ہونا تھا۔ زرین کے نانہال والوں نے اپنے گھر سے متصّل امرودوں والے باغ میں ایک عارضی انتظام کیا۔ خالی جگہیں دیکھ کر دو تین گہرے گڈھے کھدوائے۔ ان پر کھڈیاں رکھوائیں۔ ہر گڈھے کی بغل میں بڑے بڑے بالٹے بھر کر پانی رکھا گیا۔ درمیان میں اوٹ کے لئے بانس کے ٹٹّر کھڑے کئے۔ اسی طرح کچھ جگہیں گھیر کر اور پانی رکھ کر نہانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ یوں مرد کنویں پر نہاتے تھے اور عورتیں آنگن میں بانس کی چارپائیاں کھڑی کرکے۔ جنہیں زیادہ احتیاط کرنی ہوتی وہ چارپائی کے دوسری طرف کسی لڑکی یا ملازمہ کو کھڑا کر لیتیں۔ سردھونا ہوتا تو پہلے کپڑے پہنے پہنے پیڑھی پر بیٹھ کر گردن جھکا کر کھَلی یا بیسن سے سر دھولیتیں۔ پھر کچھ کپڑے جسم پر رہتے چارپائی کے پیچھے غسل ہوتا۔ اچھا خاصہ جھمیلا ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ جھمیلا زندگی کا ناگزیر حصہ بن کر قابل قبول تھا۔ کسی کو کہیں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی تھی۔
بارات میں غراروں کے بڑے بڑے پائینچے پھڑکاتی، تُلواں دوپٹے اوڑھے دولہا کی ماں، بہنیں، چچیاں، پھوپیاں اور ازیں قبیل خواتین اچھی خاصی تعداد میں آئی تھیں۔ دلہن کے گھر پہنچتے پہنچتے ویسے ہی حلیہ بگڑ چکا تھا۔
واپس آکر دولہا کی والدہ نے مشاطہ کو بہت ڈانٹا۔
’’اوئی بیوی یہ کہاں اللہ میاں کے پچھواڑے رشتہ طے کرایا تھا۔ مرے گنواروں کے گھر نہ نہانے کی جگہ نہ ہگنے موتنے کی۔ ‘‘ پھر انہوں نے نئی دلہن یعنی زرین کی امی سے، جو اس وقت محض چودہ پندرہ برس کی تھیں، کہا، بیوی، تمہارے گھر کسی کا پیٹ نہیں خراب ہوتا؟ ہوجائے تو کیا وقت بے وقت پچھایا کھول کھول کر کھیتوں میں بیٹھتی ہو۔ اور جو بھاگتے بھاگتے کپڑوں میں ہوجائے …‘‘ ان کی زبان پر لگام تو کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ یوں بھی عمر بڑھنے پر خواتین کا منہ کھل جایا کرتا تھا۔ (ہاں اب عمر بڑھنے کی قید نہیں رہ گئی تھی) زرین کی کم سن ماں شرم سے پانی پانی ہوجاتیں۔ یہ بھی نہ کہہ پاتیں کہ ہم لوگ کھیتوں میں نہیں اپنے ہی باغ میں جاتے ہیں اور وہاں صرف عورتیں جاتی ہیں۔ مرد یا بسواڑی جاتے ہیں یا کھیت۔ ’’نیک بخت! دولہا کے والد نے کہا۔ شیوخ کا خاندان ہے۔ لڑکی خوبصورت، میلاد کی کتاب سنا کہ پڑھ لیتی ہے۔ کھیت کھلیان والے لوگ ہیں۔ لڑکی کو حصہ بھی ملے گا۔ اب تم روز کون سا ان کے گھر جائو گی کہ تمہیں بیت الخلا کی اتنی شکایت ہو گئی۔ ‘‘
’’دلہن بھی تو بیل گاڑی میں رخصت ہوئی۔ ہمیں دلہن کے دروازے ہچر ہچر کرتی بیل گاڑیاں لے گئیں۔ ‘‘
’’ٹھیک ہے۔ اب مت لانا کوئی لڑکی وہاں سے۔ لیکن خاموش تو ہو جائو۔‘‘
’’سمدھیانے میں شادی بیاہ ہوگا، بلاوا آئے گا تو نہ جائیں گے؟‘‘
ہگنے موتنے کی جگہ تو اب بھی الگ نہیں تھی۔ (دُور دراز کہیں بیٹھے لوگ عظیم الشان مندر بنانے کی تیاریاں کرنے یا تیاری کی دھمکیاں دینے میں مصروف تھے۔ لوگ، جو ان بنیادی سہولتوں سے محروم انسانوں کے کاندھوں پر سوار ہوکر اپنے اپنے تخت شاہی پر قدم رکھا کرتے تھے۔ ) بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، اسکول بہت تھے، ہیلتھ سنٹر کام نہیں کر رہے تھے۔ بس ہاں لوگ اب فاقوں سے نہیں گذرتے تھے جیسے کبھی چندھی بُوا کا خاندان گذرا تھا اوردو وقت کی روٹی کے لئے اپنی گیارہ برس کی بیٹی کو دوسروں کے حوالے کر گیا تھا۔ اب سب لوگوں کو دال بھات ہو یا آلُو روٹی، دونوں وقت کھانا مل جایا کرتا تھا۔ کچھ کنبے خوشحال بھی ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو گائوں سے باہر چلے گئے تھے۔
شاید کوئی اب دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو گائوں سے باہر جھاڑو برتن کرنے نہیں بھیجتا ہوگا اور بزرگوں کو ہری تو قطعئی نہیں بُلایا جاتا ہوگا۔
ہری بول
زرین کو اس کی ماں نے بتایا تھا اور زرین کی ماں کو ان کی ماں نے۔ یہ مائوں کا سلسلہ جوڑا جائے تو ابتدائے آفرینش تک چلتا چلا جائے گا۔ ہر ماں کی ایک ماں ہوتی ہے اور پھر اس ماں کی بھی اپنی ماں … اور … دماغ خراب ہو جائے گا۔ جوڑتے جائو۔
اور یہ تو تین نسل پہلے کی ہی بات ہے۔
تب زرین کی نانی نئی شادی شدہ تھیں اور اس گھر میں بہو بن کر آئی تھیں۔
رات خاصی جا چکی تھی۔ وہ شوہر کا انتظار کرتی بیٹھی تھیں۔ خدائے مجازی کے آنے سے پہلے سو جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن نئے سہاگ کی جاگتی راتوں کا شا خسانہ نیند کا غلبہ۔ آنکھیں جھُکی جاتی تھیں۔ اماوس کی رات تھی۔ سیاروں کی ہُواں ہُواں، الّووں کی ہُو ہُو۔ ہوا میں درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ۔ ماں باپ بھائی بہنوں، چچی خالہ پھوپی سے بھرے گھرسے آئی چودہ برس کی کچی عمر کی وہ ڈری سہمی لڑکی سسرالیوں کے درمیان بتیس دانتوں کے بیچ زبان جیسی۔ ابھی تو شوہر سے بھی سوائے ایک تکلیف دہ جسمانی تعلق کے اور کسی تعلق کا احساس نہیں پنپا تھا۔ تبھی اس تنہا، طلسمی، ڈرائونے ماحول میں وہ آوازیں بھی سرسرائیں۔ یوں جیسے پچھلی پیریاں گھاگھرے گھماتی الٹے پنجوں پر رقص کناں ہوں۔ ان آوازوں میں کرب تھا، احساس گناہ تھا، نوحہ تھا، طلسم تھا اور تھا شانوں کے اوپر سے دانت نکالے مسکرا کر جھانکتی ہوئی موت کا خوف ہری بول، ہری بول، بول بول ہری ہری — پھر ان آوازوں کے ساتھ کوئی گھُٹے گھُٹے گلے سے رونے بھی لگا جیسے کسی پچھلی پیری نے گھومتے گھومتے کسی کو اپنے گھاگھرے تلے لے لیا ہو اور اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ رونے کی آواز کسی مرد کی تھی۔ پھر وہ ساری آوازیں اپنے سارے کرب، اپنے سارے طلسم اپنے سارے گناہ کو سمیٹے قریب آتی گئیں۔ بالکل اس کے گھر کے حاطے کے پیچھے جہاں امرودوں کا باغ تھا۔ پھر ہولے ہولے وہ بسواڑی کی طرف نکل گئیں۔ بسواڑی کے پاس سے ہوکر ندی گذرتی تھی، تِرل رِل کرتی، بے پروا، بے نیاز، اپنے لا زوال حسن کے غرور میں گُم کنارے کے سبزہ زاروں پر خنداں۔
نئی دلہن کے شوہر رات گئے کمرے میں آئے (نانی نے زریں کی ماں کو بتایا تھا کہ ان کے وقت میں مرد رات کو چوروں کی طرح چپکے سے بیوی کی خوابگاہ میں داخل ہوتے اور صبح کی روشنی پھوٹنے سے پہلے چوروں کی طرح ہی نکل لیا کرتے تھے) تو دلہن کی گھگھی بندھی ہوئی تھی۔ بدقت تمام اس نے بتایا کہ گھر کے آس پاس بد روحیں رہتی ہیں۔ ابھی ان کا جلوس جا رہا تھا۔ کوئی ان کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ شاید بہت بوڑھا تھا وہ۔ دولہا کی گود میں سمٹ کر دلہن کے دانت بھنچنے لگے۔
دوسرے دن دولہا کی والدہ نے کم سِن بہو کو سمجھایا۔ ہم، نجیب الطرفین شیوخ، شاہ چاند کے مرید ہیں۔ ہمارے یہاں سایے جھپیٹے کا گذر نہیں۔ وہ گائوں کے کنارے رہنے والے غریب کمیے ہوں گے۔ کسی بوڑھے کو ہری بُلانے لے جا رہے ہوں۔ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔
دلہن نے گھونگھٹ ذرا سا سرکا کر سوالیہ آنکھوں سے مادر ملکہ کو دیکھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہری بُلانا؟ وہ اب بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔
ادھر بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں۔ کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں۔ یہاں تک سنا کہ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، اسے ابال کر نمک لگا کر کھا لیتے ہیں۔ اب گھر میں کوئی بہت بوڑھا کھٹیا پہ پڑا دو وقت روٹی مانگے اور پیشاب پاخانہ سمیٹنے کی خدمت تو ایک دن اسے مقدور کے مطابق بھر پیٹ اچھا کھانا کھلاتے، پھر رات گئے کھاٹ پر ڈال کر ہری بول ہری بول کہتے ندی کے سپرد کر آتے ہیں۔
’’زندہ کو!‘‘ساری حیا بھول کر، آنکھیں کھول کر دلہن زور سے بول پڑی۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ بہا تھا۔ مادر ملکہ ملازمہ کو ہدایت دینے کے لئے اٹھ گئیں کہ ڈھیکی میں دھان کوٹنے کے بعد چاول کہاں رکھنے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے اور یہ کہ بہُو کو آواز اونچی کرکے بڑوں سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ ارے مُردے کو کوئی ہری بول ہری بول کرتا لے جائے تو اس میں بتانے جیسی کیا بات ہے۔ زندہ کو لے جاتے ہیں تب تو… کیسی کم عقل بہو آگئی ہے۔
اب ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ زرین کے جسم میں پھر بھی جھر جھری دوڑ گئی۔ گھر میں کچھ دن قبل انتقال کرنے والے ماموں کی قبر کی مٹی کی مہک تھی۔ زرین جس حجرے میں تھی وہ تازہ تازہ لیپا گیا تھا۔ اور مٹی تو یہاں سے وہاں تک ایک تھی۔ کھیت کھلیان، دیواریں، قبرستان۔ وجود کو پیدا ہونے والے دن سے ہی کھانا شروع کر دینے والی مٹی۔
کمرے میں باندھ کی بنی چارپائی پر کھیس ڈال کر ہینڈلوم کی موٹی رنگین چادر پڑی تھی اور سیمل کی روئی بھرا تکیہ رکھ کر زرین کے بستر کو حتی الامکان آرام دہ بنایا گیا تھا۔اسے خاص کمرہ دیا گیا تھا جس میں ہلتی سلاخوں والی کھڑکی تھی جو حاطے میں کھلتی تھی۔ حاطے کے پار نظریں دوڑانے پہ گائوں کے سر سبز کھیت نظر آتے تھے اور برگد کا وہ پرانا جغادری درخت جس کے سامنے اس گھر کی کئی نسلیں گذر گئی تھیں۔ کونے میں رکھی ایک تپائی پر کسی بھتیجی کے ہاتھ کا کروشیا کا بُنا کور ڈالا ہوا تھا۔ اس پر المونیم کے بڑے سے گلاس میں پانی رکھ دیا گیا تھا۔ طاقچے میں چراغ روشن تھا۔ سونے سے پہلے زرین نے اسے پھونک مار کر بجھا دیا۔ بیل گاڑی نے جوڑ جوڑ دُکھا دیا تھا۔ جگہ بدلنے اور بستر کی سختی کو محسوس کرنے کے باوجود اسے نیند آگئی۔
رات شاید آدھی گذری تھی حاطے میں کھڑے نیم کے پرانے چھتنار درخت میں چھپے الو جاگ جاگ کر فعال ہو اٹھے تھے۔ پھر شاید کسی الو نے کسی چھوٹے پرندے کو دھر دبوچا۔ اس کی تیز درد ناک چچیاہٹ اور الو کی حق ہُو کی منحوس آواز نے زرین کو جگا دیا۔ ایک بار نیند کھُل جائے تو دوبارہ جلدی آتی نہیں تھی۔ گٹھیا زدہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھیں۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ نیند کھُل جائے تو ٹائلٹ جانا ضروری۔ ذرا بھی دیر ہوتی تو پیشاب کے قطرے کپڑوں پر لگ جاتے۔ یہاں اٹیچڈ باتھ روم کا کیا کام۔ نہایت ابتدائی سطح کا بیت الخلا حاطے کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ بانس کا فریم کھڑا کرکے اس کے گرد ٹاٹ لپیٹ کر پردہ کردیا گیا تھا اور اندر گہرے گڈھے کے اوپر قدمچہ فٹ تھا۔ پاس میں پانی کا بڑا سا ڈرم رکھا ہوا تھا۔ ہوا نیم کے خشک پتے اڑا کر اکثر پانی میں گرا دیتی تھی جو ڈرام میں تیرتے رہتے تھے۔ سر پر چھت نہیں تھی اس لئے اگر برسات ہو رہی ہو تو لوگ چھاتہ لے کر یا کپڑا سر پر ڈال کر جاتے تھے۔ لوگوں کو اس انتظام سے کوئی دقت نہیں تھی۔
ہُو حق… ہُو ہُو ہُو … ایسا لگا جیسے الو کھڑکی کے بالکل قریب آکر بولنے لگا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔ دل کو سمجھایا آخر ایک پرندہ ہی تو ہے۔ سارے الٹے سیدھے خیال ہمارے ذہن کی اُپج ہوتے ہیں لیکن خوف منطق سے ہارتا نہیں۔ جب سالوں تک کسی جگہ نہ آیا جائے تو وہ جگہ نئی ہو جاتی ہے۔ خواہ نانہال ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایسا نانہال جہاں فضا میں اپنے قدموں کی چاپ چھوڑتی موت بس آکر گزری ہی ہو۔ گھبراہٹ نے حاجت کو تیز کردیا۔ مجبوراً وہ اٹھیں۔ تین چار دن رہنا ہے۔ کل سے وہ چندھی بُوا کو اپنے ساتھ سُلا ئیں گی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ چندھی بوا کو رتوندھی آتی ہے۔ ان کی نظر تو شام ہوتے ہی دھندلانے لگتی ہے۔
’’کوہے؟‘‘ بُوا ادسارے میں مٹی کے فرش پر ایک پتلی چادر ڈالے سو رہی تھیں۔ ہڑ بڑا کر کروٹ بدلی تو چادر سمٹ کر گولا بن گئی۔
’’سوجائو، سو جائو، ہم ہیں۔ ‘‘ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی حاطے میں آگئیں۔ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے قینچی سے اس کی ایک قاش کاٹ کر آسمان سے لٹکا دی ہو۔ نیم کا جغادری پیڑ بھوت جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ چھتری میں کہیں کسی معصوم پرندے کی تکا بوٹی کرتا گول گول آنکھوں سے دنیا کو گھورتا، منحوس آواز یں نکالتا الو چھپا بیٹھا تھا۔ گھنے باریک سبز پتوں پر شطرنجی بنتی ملگجی چاندنی اندھیرے سے بھی زیادہ ڈرائونی لگ رہی تھی۔ زمین ناہموار تھی اور حاطہ وسیع۔ اس پر چل کر ٹٹّر ہٹا کر اندر داخل ہونے اور سنبھل کر اکڑوں بیٹھنے میں اتنی دیر لگی کہ شلوار میں چُلّو بھر پیشاب لگ ہی گیا۔ بے حد کبیدہ خاطر ہوکر وہ لوٹیں۔ بیگ سے بدقت تمام دوسری شلوار نکال کر بدلی۔ صبح چندھی بُوا کو دھونے کے لئے دے دیں گی۔
چندھی بوا
زرین کے سارے کام ایک عرصے سے چندھی بُوا کے ذمے تھے۔ سایے کی طرح ساتھ لگی رہا کرتی تھیں۔ زرین کو اطمینان تھا اس لئے کہ وہ عمر میں اس سے خاصی چھوٹی تھیں۔ بس کوئی پچاس پچپن کے لپیٹے میں۔ اب حادثوں اور ناگہانی کی تو کوئی نہیں جانتا لیکن نارمل عمر پائی تو آخر وقت میں زرین کے پاس ہوں گی۔ وہ زرین کی عادت بن گئی تھیں۔ ان کے آس پاس رہنے سے زرین کو بڑے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ مرضی کے مطابق پکا ہوا کھانا مل جاتا۔ نہانے سے پہلے گیزر میں گرم پانی، کپڑے،تولیہ تیار ملتے۔ عمر کے اثر سے لڑ کھڑاتے قدم سنبھل جاتے، مالش سے جسم کا درد نکل جاتا۔ پیشاب کے قطروں سے ناپاک ہوئی شلوار انہیں لقماتے ہوئے کسی شرمندگی کا احساس نہ ہوتا۔ صبح کو یہاں بھی وہ زرین کی عزت بچا لیں گی۔ کہیں گی ہماری بی بی کو ایسے بیت الخلا میں جانے اور پر ڈرام سے مگ میں پانی لے کر آبدست کی عادت نہیں ہے۔ ہاتھ بہکا تو پانی کپڑوں پر چلا آیا۔ اب بی بی کو تو کیا خود ہمیں ایسی جگہ جانے کی عادت نہیں ہے۔ مگر ہاں ہمیں رات کو اٹھنا نہیں پڑتا۔ رتوندھی نہ آتی ہوتی تو ہم رات کو بھی بی بی کے ساتھ اٹھ جاتے۔ بولنے کی عادت ٹھہری اور بھی جانے کیا کیا بک بک کریں گی۔ بس بی بی پہ حرف نہ آئے۔
چندھی بوا کا نام مولوی صاحب نے قرآن شریف دیکھ کر بی بی سارہ خاتون رکھا تھا۔ بی بی اور خاتون تو چھوڑ دیجئے وہ سارہ بھی نہ رہ گئیں۔ پانچ چھ سال کی تھیں کہ رتوندھی آنے لگی۔ گھر میں اس طرح کے جملے گونجنے لگے … ’’اے ہے چندھی دیکھ کے۔ ‘‘ ’’ارے اس چندھی کو شام پڑے کیا کرنے کو کہہ دیا سب الٹ پلٹ کردے گی۔ ‘‘ ’’ایک تو لڑکی، اوپر سے چندھی۔ بے چارے ماں باپ کی قسمت‘‘ ہوتے ہوتے وہ صرف چندھی کہلانے لگیں گرچہ دن میں تو انہیں ٹھیک ٹھاک ہی دکھائی دیتا تھا۔ تو لوگ دن میں سارہ کہہ لیا کریں، بلا سے رات برات چندھی کہہ لیں۔ ایک بار انہوں نے یہ کہا تو لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہوگئے۔ گیارہ برس کی عمر میں انہیں نانہال کی طرف سے زرین کو دے دیا گیا۔ بدلے میں ان کے ماں باپ کو ایک زمین کے ایک چھوٹے سے قطعہ پر چھپر ڈال کر اسے ان کے نام لکھ دیا گیا۔ ان دنوں وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے نکال دئیے گئے تھے۔ زرین کے نانا کے رابطے میں آنے پر میاں بیوی اور سات آٹھ برس کے لڑکے نے زرین کے نانہال کے کھیتوں میں بطور مزدور کام کرنا شروع کردیا تھا۔ چار بر س کی بی بی سارہ خاتون کو گھر میں خواتین کے حوالے کر کے بھُلادیا گیا۔ پلنگ بھر زمین پر پڑا چھپر گیارہ برس کی اس لڑکی کی قیمت تھی جو اتنی سی عمر میں مسالہ پیستی، روٹیاں پکاتی، ڈھیکی میں دھان کوٹنے میں ہاتھ بٹاتی، اپلے پاتھتی اور اپنی بینائی کے نقص کے باوجود لڑ کھڑاتی، ٹھوکریں کھاتی دیر شام تک سارے گھر کے احکام بجا لاتی رہتی۔ خرید و فروخت کی یہ تاریخ خاصی پرانی تھی۔
چندھی بوا کے ہندو پر دادا بنگال کے قحط کے دوران اپنی حاملہ بیوی کو گائوں کے ایک کھاتے پیتے مسلمان کسان کے گھر بیچ کر چل دیے تھے۔ کسان نے جتایا بھی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بنگلہ کی کسی نواحی بولی میں سمجھایا کہ اس وقت انہیں مذہب سے زیادہ اپنی اور اپنی بیوی بچے کی جان کی فکر ہے کسان نے رکھ لیا تو تینوں بچ جائیں گے۔ کچھ کھانا اور چند سکے لے کر وہ قحط کا مارا، لاغر کمزور جوان چل دیا اور پھر پلٹ کر نہیں آیا۔ شاید مر کھپ گیا ہوگا۔ رقم زیادہ دن نہ چل سکی ہوگی۔ یہاں حاملہ بیوی کا انتظام ہوگیا تھا۔ بیٹا پیدا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ماں بیٹے نے اپنے مالکوں کا مذہب قبول کرلیا۔ کھیت مزدوروں کے درمیان شادی بیاہ ہوے اور تیسری نسل میں بی بی سارہ خاتون پیدا ہوکے پانچ برس کی عمر میں زرین کے نانا اور گیارہ برس کی عمر میں زرین کے یہاں چلی آئیں کہ سال بھر کے اندر پیدا ہو جانے والے دو بچوں کی پرورش میں ہاتھ بٹائیں۔
بچے بڑے ہوگئے۔ خدا ترس زریں نے بی بی سارہ خاتون عرف چندھی کی شادی کرادی۔ چھوڑ چھاڑ کے ایک عدد جھولا، ایک ٹین کا بکس لے کر بھاگ آئیں۔ ’’ہمارا جی نہیں لگتا۔ مرے موٹا کھانے والے گنوار۔ اوپر سے اس کی اماں روز دن جھگڑا کراتی ہے اور جب وہ ہمیں مارتا ہے تو آرام سے حقہ گڑ گڑاتی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن کسی نے کہا سمجھائو بیٹے کو، بہُو پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو دھواں چھوڑتے ہوئے بولی ’ ’ہم کیا سمجھاویں گے۔ مرد۔ مہرارو کا جھگڑا ہے، سمجھیں آپس میں۔ بڑی حرامی ہے۔ ‘‘
زرین نے بہت ڈانٹا۔ کچھ بھی ہو بد زبانی کیوں کر رہی ہو۔ پھر لاکھ سمجھایا۔ ٹس سے مس نہیں ہوئیں۔ آخر کو خلع دلوانا پڑا۔ زرین کے یہاں دو بارہ یوں رچ بس گئیں جیسے کبھی گئی ہی نہ ہوں۔ ایک مناسب رشتہ پھر طے کرایا گیا۔ منہ بگاڑ کے نکاح کے وقت ہاں تو کہہ دی لیکن سال پیچھے پھر زرین کے پھاٹک پر رکشہ آن کے رکا اور جھولا لٹکائے بوا بر آمد ہوئیں۔ دن میں ہی الووں کی طرح آنکھیں پٹپٹا رہی تھیں۔ اس مرتبہ ٹین کا بکسا بھی چھوڑ آئی تھیں۔ اور اس مرتبہ خلع بھی نہیں مانگا۔ ’’اب تیسرا تو ہرگز نہیں کرنا۔ فار خطی لے کے کیا کریں گے۔ ’’کچھ دن اس دوسرے شوہر نے انتظار کیا پھر ہار کر دوسری شادی کرلی۔ بال بچوں میں مگن ہوگیا۔ بوا اس کے نام کے ساتھ گائوں تک کا نام بھول گئیں۔ بس عید کے عید کامدار چوڑیاں ضرورر پہنتی تھیں اور گلابی دوپٹہ اوڑھا کرتی تھیں۔ اب وہ چندھی بُوا کہلانے لگی تھیں۔ زرین کو سخت کوفت ہوتی تھی لیکن گھر کے دوسرے افراد خاص طور پر صفائی کرنے والی ملازمہ اور مالی نے انہیں یہ خطاب دیا تھا جو قبول عام کی سند اختیار کرگیا۔ انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اب اللہ میاں نے ہمیں چُندھا کردیا تو بندوں کا کیا۔ کہیں گے ہی چندھی بُوا۔ رفتہ رفتہ لوگ ان کا نام بھول گئے۔ بھول جائیں بلا سے۔ ان کے لئے تو زرین بی بی اور ان کی اولادیں ہی سب کچھ تھے۔ بیٹا جرمنی سدھارا تو سب سے زیادہ چندھی بوا کو صدمہ ہوا کہ ایک ہی پوت اور ہماری بی بی کو چھوڑ کر سات سمندر پار چلا گیا۔ زرین کے شوہر کے انتقال کے بعد سے وہ سایے کی طرح زرین کے ساتھ رہنے لگی تھیں۔ اس وقت بھی انہوں نے ہی ساتھ دیا تھا ورنہ اولادیں — ایک تو اپنی اپنی دنیا میں گم۔ اوپر سے تین تلّہ آنے کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرنے والی۔ ماں کے نانہال سے کیا واسطہ جب اپنے ہی نانہال سے زیادہ مطلب نہ رکھا۔ ’’امی کیا کریں گی جاکے۔ اللہ میاں کا پچھواڑہ ہے۔ پھر جو مرگیا وہ آپ کے جانے سے واپس آنے سے تو رہا۔ ‘‘اس جملے میں پنہاں منطق کا تو واقعی جواب نہیں تھا۔
’’امی، آپ سے وہاں کا سفر برداشت نہیں ہوگا۔‘‘ بار بار اس جملے کو دوہرایا گیا
’’ہم ہیں نا بھیا۔ جانے دو بی بی کو۔ ان کی نال وہاں گڑی ہے‘‘ چندھی بُوا نے کہا۔
’’چندھی بوا، نال تو تمہاری گڑی ہے۔ دراصل اسی کو کھودنے جا رہی ہو۔ امی کو چھوڑو، تمہیں ہو آئو۔‘‘
زرین کی ضد اور بوا کی حمایت کے آگے اولادوں کی ایک نہ چلی۔ ویسے بھی یہاں رہتا کون تھا۔ ساری دلیلیں تو فون پر ہی دی جا رہی تھیں۔ ڈھنڈار گھر میں ساتھ نبھانے کو چندھی بُوا ہی تھیں۔ دو۔ دو بار شوہروں کو چھوڑ کر بھاگ آنے کے لئے کیسی کیسی گالیاں انہوں نے کھائی تھیں۔ دوسری مرتبہ تو زرین نے پنکھیا سے دو چار ہاتھ بھی جڑ دیے تھے لیکن آج لگتا تھا، کہ زرین کے لئے انہیں اللہ نے مقرر کیا تھا۔ واقعی صبح کو انہوں نے وہی سب کہہ کر جو زرین نے سوچا تھا، شلوار دھوکر پھیلا دی۔
جرمن بہو
زرین کی بہو پر ’میڈ اِن جرمنی‘ کا ٹھپہ لگا ہوا تھا۔
کمپیوٹر انجینئرنگ کرنے کے بعد بیٹا جرمنی چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے آگے کی ڈگری بھی لی اور ملازمت بھی کی۔ اس وقت زرین کے شوہر حیات تھے اور اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زرین نے اس کے لئے کئی لڑکیاں نظر میں رکھ چھوڑی تھیں۔ وہ اس وقت تک اپنی انسٹرکٹر کے ساتھ رہنے لگا تھا جو عمر میں اس سے چند سال بڑی لیکن بہت حسین تھی۔ والدین سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی اسی لئے جو تصویر بھیجی جاتی، دیکھ لیتا پر معقول بہانہ بنا کر ٹال جاتا تھا۔ دو سال کی ٹال مٹول کے بعد والدین کو احساس ہوگیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تبھی، خوش قسمتی ((یا بد قسمتی ) سے وہ لڑکی رشتے کو شادی میں بدلنے پر راضی ہوگئی اور بیٹے نے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتا کر کہہ دیا کہ وہ بد مزگی نہ پیدا کریں، خوشی خوشی یہاں آکر شادی میں شریک ہوں۔ ریٹرن ٹکٹ بھیج دیا جائے گا۔ ورنہ شادی تو ہونی ہی ہے۔
دل کو سمجھا بجھا کر، خود اپنے آپ کو بہت ساری دلیلیں دے کر میاں بیوی نے رضا مندی دے دی۔ زرین نے تلواں غرارہ، چھپکا، جھومراور لانبے لانبے جھمکے بنوائے اور شوہر کو ساتھ لے کر جرمنی روانہ ہوئی۔ دلہن اور اس کے گھر والے ان چیزوں سے بہت محظوظ ہوئے۔ لباس ان کے لئے فینسی ڈریس جیسا تھا۔ گوری، بقول چندھی بوا بندر یا جیسی صورت والی جرمن دلہن بڑے معرکے کی ہندوستانی دلہن بنی۔ چرچ ویڈنگ میں تو خیر اس نے گائون ہی پہنا تھا۔ یہ نکاح کا ’گیٹ اپ‘ تھا۔
چندھی بُوا از حد رنجیدہ تھیں۔ بھیا کی شادی کے کیسے کیسے ارمان تھے۔ لڑکیاں دیکھنے جائیں گی۔ دو چار کو لڑکی والوں سے خوب خاطریں کرانے کے بعد ریجیکٹ کیا جائے گا۔ پھر کسی ایک کے لئے ہاں کہنے کے بعد منگنی، بری کی تیاری، شادی کی رسمیں، سمدھنوں کو گالیاں، جہیز میں عیب نکالنے سے لے کر پھر دلہن پر صدقے واری جانے تک نہ جانے کتنا کچھ۔خیر جب بی بی ان سارے ارمانوں پر پانی پھیر کر، گھر پر انہیں تنہا چھوڑ کر بیاہ کے لئے گئیں تو دیر شام کو اکیلے گھر میں انہوں نے ہفتہ بھر تک ڈھولک ٹھنکائی اور خوب گیت گائے۔ مالی کی بیوی اور جھاڑو برتن کرنے والی چندا کو بلا کر چائے بسکٹوں سے تواضع بھی کردیا کرتی تھیں۔ تینوں ساتھ مل کر زمانے اور فرنگیوں سب پر لعنت بھیجتیں جو بھیا کو ورغلا کرلے اڑے تھے۔
بھیا ایک بار ’دلہن ‘ کو لے کر ہندوستان آئے تھے۔ بجائے اسے اپنی زبان سکھانے کے اسی کی زبان سیکھ لی تھی۔ پھر انگریزی بھی دونوں کے درمیان مشترک تھی۔ زرین کا کام چل جاتا تھا لیکن بہو سے گپ شپ کرنے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ماموں چچا کی بخیہ ادھیڑنے کے جو ارمان باقی بچے تھے وہ بہو کی صورت دیکھنے کے باوجود دل کے دل میں رہ گئے۔ انہوں نے اسے گھوڑے جیسے منہ والی قرار دیا اور کہا کہ بھیا کا وہی حال ہے کہ جات ملی نہ بھات۔ بہر کیف سسرال والوں سے مل کر، تاج محل دیکھ کر، مچھروں مکھیوں اور ’دہلی بیلی‘ (Delhi belly)سے پریشان ہوکر دلہن واپس سدھاریں۔
سولہ سترہ برس گذر گئے۔ دو بیٹے ہوئے جن کی محض تصویریں دیکھنے کو ملا کرتی تھیں۔ زرین اور اس کے شوہر ایک بار اور بچوں کے لالچ میں جرمنی ہو آئے۔ اور جب بچے اچھے خاصے ٹین ایجر ہو رہے تھے اور زرین کو اس رشتے کی طرف سے اطمینان ہوگیا تھا، اچانک طلاق کی اطلاع ملی۔ (دُکھ بانٹنے کو اب اس کے شوہر نہیں رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر و صیت تبدیل کرائی تھی اور مکان زرین کے نام کردیا تھا۔ زیادہ تر کیش کینسر کے علاج، جرمنی جانے اور بچوں کو بھاری تحفے دینے میں خرچ ہو چکا تھا مگر ہاں ایک اچھی سرکاری نوکری کی معقول فیملی پنشن زرین کے لئے تھی۔ )
بولو بولو، ہری ای ہری
وہ کالونی رٹائرڈ لوگوں کی کالونی کہلاتی تھی۔ کسی زمانے میں وہاں بڑا سا جھیل نما تالاب تھا۔ لوگ بطخوں اور مرغابیوں کے شکار کو آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بزرگوں کے وقت کی ہے۔ آج کے بزرگ نہیں بلکہ ان بزرگوں کے بزرگوں کے وقت کی۔ پھر ایسا ہوا کہ تالاب میں پانی کم ہونے لگا۔ مرغابیوں نے آنا بند کردیا۔ زمین نکل آئی۔ وہ زمین بہت سستی بکی۔ لوگ کہتے تھے کون جائے گا وہاں رہنے۔ پانی تو ختم ہوا لیکن اب بھی گیدڑ اور الو بولتے ہیں۔ کوئی بیمار پڑے تو دوا نہ ڈاکٹر۔ عقلمندوں نے وہاں دھڑا دھڑ زمینیں خریدیں اور خرید کر چہار دیواری کرا کے ڈال دیں۔ پھر مکان بھی بن گئے۔ آج کے کثیر منزلہ عمارتوں کے گھُٹے گھُٹے فلیٹوں کے مقابلے وہ محل جیسے لگتے۔ آگے وسیع اور سبز لان، پورٹیکو، بڑا سا بر آمدہ پھر اصل عمارت۔ نازک ستونوں پر ایستادہ وہ بنگلے کولونیل ہندوستان کی یاد دلاتے تھے۔ وہاں رہنے والے بھی زیادہ تر سرکاری افسر ہی تھے۔ پھر وہاں رفتہ رفتہ ایک تبدیلی آئی۔ گھونگے جیسی رفتار کے ساتھ لیکن پچاس برس کے عرصے میں کسی جوان دل کی طرح دھڑکتی، دور سے سمجھ میں آتی تبدیلی۔ وہ پورا علاقہ ایسا منحوس لگنے لگا جیسے رہائشی مکان نہ ہوکر قبریں ہوں۔ ایک تو ویسے ہی شہر بہت روشن نہیں رہا کرتا تھا اس پر سے یہاں بیشتر گھروں میں باہر کی لائٹ روشن نہیں کی جاتی تھی۔ لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے۔ بہت سے گھر بند تھے۔ زیادہ تر گھروں میں بوڑھے، رٹائرڈ لوگ تھے۔ بس میاں بیوی۔ ایک آدھ ملازم۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ یہ کھاتے پیتے اور تعلیم یافتہ کنبے تھے جنہوں نے لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور بیٹیوں کی اچھی جگہ شادیاں کی تھیں اب یہ سارے نو جوان پھُر ہوگئے تھے۔ یا غیر ممالک میں نہیں تو پھر بمبئی، مدراس، بنگلور جیسی جگہوں میں جہاں کار پوریٹ سیکٹر میں ان کی اچھی ملازمتیں تھیں۔ چھٹیوں میں اکثر گھومنے غیر ممالک نکل جاتے۔ کبھی کبھار ماں باپ کی خبر لینے آ بھی نکلتے یا پھر زیادہ با ہمت والدین ہوے تو اولادوں کی میزبانی قبول کرکے دو چار مہینہ ان کے گھر رہ آتے۔ شہر کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس کو لونی کو’ اولڈ ایج ہوم ‘ کہنے لگے تھے۔ کچھ ستم ظریف کہتے تھے یہاں بزرگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ باہر بیٹھی اولادیں ان کی موت کا انتظار کریں اور اطلاع ملنے پر آکر فاتحہ درود کے بعد آخری بار الوداع کہہ دیں۔
اچانک کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ بڑی بڑی زمینیں، ان پر بنے وسیع بنگلے اور رہنے والے دو تین۔ وہ بھی زیادہ تر بوڑھے کھوسٹ جنہیں اتنی جگہ، زمین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایک بنگلے پر ایسی عمارت اٹھ سکتی ہے جس میں سولہ سے بیس فلیٹ بن جائیں۔ بلڈرز نے اچھی قیمتیں لگانی شروع کیں۔ کچھ لوگ مکان بیچ کر فلیٹوں میں اٹھ گئے۔ بڑے، تنہا مکان غیر محفوظ بھی تھے اور ان کا رکھ رکھائو بھی بہت مشکل تھا۔ اکثر مکانوں میں صرف دو ایک کمرے، باورچی خانہ اور ڈرائنگ روم تصرف میں رہتے۔ باقی حصہ اجاڑ رہتا۔ اکثر بند بھی کردیا جاتا۔ فیض کے انتقال کے بعد خود زرین نے اوپری منزل بالکل ہی بند کرا دی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ہَول آتا تھا، ایسی ویران لگا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا اس میں جن دخل کر لیں گے۔ کرایے پر لگا دیں تو بہتر ہوگا۔ چندھی بوا تنک کے بولیں جنوں کو مولی ساب دعا تعویذ کرکے بھگا دیں گے کرایے دار مرے پر تو کوئی جھاڑ پھونک بھی اثر نہ کرے گی۔ جسٹس احسان احمد کے مکان کو ان کے بیٹوں نے کرایے پر لگا دیا تھا، لوگ قبضہ کرکے بیٹھ گئے اب چینئی میں بیٹھ کے کرو مقدمے بازی۔
بھیا کا فون آیا جرمنی سے۔ امی آپ کیوں اس ڈھنڈار گھر میں پڑی ہیں۔ بلڈر دو سوا دو کروڑ دینے کو راضی ہے۔ بیچ کے چھٹی کیجئے۔ آپ کے رہنے کو فلیٹ الگ دے دے گا۔ زرین تھوڑی سی دیر کو ہکا بکا رہ گئی۔ یہاں بیٹھ کے تمہیں بلڈر نے قیمت کیسے بتا دی۔ یہی جوڑ توڑ کر رہے ہو۔؟
’’ بلڈر سے بات میں نے نہیں کی۔ آپا کے ذریعے کرائی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں میں یہاں کِس مالی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بہت اچھا مکان تھا وہ بیوی نے لے لیا۔ بینک بیلنس بھی alimonyمیں چلا گیا۔ اب بچوں کی پرورش کے لئے معلوم ہے کتنا دینا ہے؟ آپ کی انڈین کرنسی میں دو لاکھ ماہوار۔ ‘‘
تم واپس آجائو۔ زرین نے بے چین ہوکر کہا۔
’’آپ کیسی ظالم ماں ہیں۔ اپنے بچوں کو چھوڑ دوں ؟ یہاں رہ کر ہی ان کے قریب رہ سکتا ہوں۔ ‘‘
یہ بات میرے ذہن میں فوری طور پر نہیں آئی۔ بس منہ سے نکل گیا کہ آجائو۔ لیکن تمہیں ماں کو ظالم کہنے میں ذرا سی جھجک نہیں ہوئی۔ زرین کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ ہمیشہ ہر خواہش کے آگے سر جھکایا، بچوں کے آرام، ان کے فاعدے کو مقدم جانا۔ اب یہ مکان لے کر قبر میں تو نہیں جائوں گی۔ تمہارا مالی مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیچ دو۔ میرا کچھ انتظام کردینا۔
بیٹا جو ہندوستان آنے کے نام سے بدکتا تھا جلد ہی آگیا۔
بلڈرز ایک پلش فلیٹ کے ساتھ سوا دو کروڑ دے رہے تھے۔ فلیٹ نہیں لینے پر رقم تین کروڑ پہنچ رہی تھی۔ بھائی بہن نے مشورہ کیا۔ بہن کو ایک کروڑ مل جائے گا اور بھائی کو دو کروڑ۔ یہ رقم پردیس میں پھر سے ایک فلیٹ خریدوا دے گی۔ ذاتی مکان ہوگا تو بڑے تحفظ کا احساس ہوگا۔ جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ پھر کب امی کی حماقت سے کوئی قابض ہوگیا۔ راتوں رات انہیں اور چندھی بوا کو مار کے نکل گیا۔ لیکن تین کروڑ اس صورت میں مل رہے تھے جب فلیٹ نہ لیا جائے تو امی کہاں رہیں گی۔ ان سے کہا جائے کہ جرمنی چلئے، تو ضرور یہی کہیں گی میاں دیوانے ہوئے ہو۔ اور پھر اگر راضی ہوئیں تو چندھی بوا کو نہ چھوڑیں گی۔ اب انہیں کہاں لٹکایا جائے گا۔ ’آپا امی کو رکھنا پڑے گا۔‘ اس نے کہا۔ ’’میاں دیوانے ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے چندھی بوا بھی ساتھ میں رہیں گی۔ انہیں اگر زبردستی نکال دیا گیا تو بھی اس بلی کی طرح مالکن کے پاس لوٹ آئیں گی جسے بورے میں بھر کر گنگا پار اتار دیا گیا تھا۔ اور تم جانو بنگلور میں میرے فلیٹ میں ڈھائی کمرے، ایک ڈرائنگ کم ڈائننگ۔ اور ساس سسر آتے ہیں تو چھ چھ مہینہ رہ کے جاتے ہیں۔ بچے عاجز ہیں۔ بڑے ہو رہے ہیں ان کا سامان بڑھ رہا ہے۔ امّی کو گائوں بھیج دو۔ ہماری نانی اپنے حصے سے دست بردار ہوگئی تھیں اسی لئے ماموں اور اب ان کی اولادوں کو وہ جائداد مل گئی جو ہماری امی تک بھی پہنچی ہوتی تو کیا امی کا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آخری ایام وہاں کاٹ لیں۔ مانا کہ وہ لوگ اب پہلے جیسے نہیں رہے پھر بھی بڑا سا گھر ہے، کمرے ہیں، کچھ کھیت ہیں۔ پاپا کی پینشن ہے۔ کچھ ہم لوگ دے سکتے ہیں۔ خرچ ان کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس رکھ لیں ان دونوں کو۔
’’گائوں کی کھلی فضا، ہرے بھرے کھیت، کنارے بہتی ندی۔ یقیناً امی کی لائف بڑھ جائے گی۔ امی آپ وہیں چلی جائیں۔ آخر آپ کی جڑیں وہاں ہیں۔ ہم نے پوچھ لیا ہے۔ لوگ راضی ہیں۔ انہیں ہر ماہ رقم دے دیا کریں گے‘‘۔
زرین کو چپ لگ گئی۔ چندھی بوا نے کہا ہماری بی بی کو کچھ ہو جائے گا۔ مر جائیں گی بے موت۔ ارے وہاں تو ہم نہ رہ سکیں، غریب، بِکے ہوئے ماں باپوں کی اولاد اب تو ہمیں بھی یہاں کا چسکا لگا ہوا ہے۔ امی کی لیف بڑھ جائے گی! ارے دشمنوں سے دور کل کی مرتی آج مرجائیں گی ہماری بی بی۔ پھر کبھی کہتیں۔ ماں سے زیادہ چاہے پھا پھا کٹنی کہلائے۔ کیا ہم اولاد سے زیادہ محبت کرلیں گے؟ ہمیں کیا۔ مگر ہم نا جاتے ایسے گائوں۔ سال بھر ہی تو ہوا کہ ماموں صاحب کے مرنے پہ دیکھ کے آئے کہ کیا حشر ہوگا۔
بچے کو رقم کی ضرورت ہے۔ آخر کو زرین نے چپ توڑی۔ وہ جرمن ناگن ڈس گئی تو زہر ہمیں ہی اتارنا ہے۔ ہم یہ مکان لے کر قبر میں جائیں گے؟ رہنا تو اب دو گز کے گڈھے میں ہے۔ ہمارے لئے شہر کیا اور گائوں کیا۔ بُوا تم چاہو تو یہاں کسی کے یہاں رہ لو۔اولاد پیدا کرنے کا درد جھیلا اب یہ درد بھی ہم تنہا جھیل لیں گے۔
بُوا سر یہ دو ہتّڑ مار مار کے رونے لگیں۔
’’تو چلو پھر۔‘‘
مکان بکنے کی کاغذی کارروائی مکمل ہوگئی۔ روپیہ ٹرانسفر ہونے کا انتظام ہوگیا۔ بیٹے نے دبی زبان سے کہا کہ امی کی طرح اس کی بہن بھی اس کے حق میں اپنے شرعی حق سے دستبردار ہو جائے مگر بہن نے ظاہر کیا کہ وہ کوئی ایسی بات سننے کو تیار نہیں اور ضرورت پڑنے پر قانون کا سہارا لے سکتی ہے۔ خیر باقی رقم بھی بہت کافی تھی۔ اس نے چھٹی کچھ بڑھائی اور امی کو خود ان کے نانہالی گائوں پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ان کی نانہال ہو آئے گا۔ لوگ خوش ہو جائیں اور جاتے جاتے امی کو وہ کچھ خوشی دے جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ گیا، ان کا آبائی وطن دیکھا۔ اس نے بڑی سی ائیر کنڈیشنڈ آرام دہ جیپ کا انتظام کیا تاروں کی چھائوں میں امی اور چندھی بوا اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ سوار ہوئیں۔ امی کی ضد پر ان کے طوطے کا پنجرہ بھی ساتھ رکھا گیا۔
زرین نے ایک آخری نظر اپنے شوہر کے بنوائے ہوئے ارمان بھرے وسیع و عریض دو منزلہ مکان پر ڈالی۔ کروندے کی جھاڑیوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ سڑک کے اس پار تیل اور سندور پُتے ہوئے تنے والے برگد کے نیچے چراغ روشن تھا اور تنے پر سرخ دھاگے لپٹے ہوئے تھے۔ عورتیں اس کے گرد گھوم گھوم کر بٹ ساوتری کے موقعے پر پوجا کرتی اور شوہر کی لانبی زندگی کی تمنا کرتے ہوئے سرخ دھاگے لپیٹا کرتی تھیں۔ اب یہاں چار منزلہ عمارت بنے گی۔ ہر فلور پر چار چار فلیٹ۔ اس طرح یہاں سولہ کنبے رہیں گے۔ زرین کے دل میں ہُوک اٹھی۔ اسی وقت پتوں میں چھپا اُلو رات کے آخری پہر کی بولی بول اٹھا۔ حق ہُو … حق ہُو۔ کیا برگد کی گھنی چھتری میں چھپی پچھل پائیاں اترنے لگی تھیں ؟ زرین نے گھبرا کر چندھی بُوا کے شانوں کا سہارا لیا۔
امی چلیں — بسم اللہ۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی۔
ہری بول ہری بول … یہ آوازیں کہاں سے آرہی تھیں ؟ بیٹی نے تو فی امان اللہ کہا تھا اور بیٹے نے بسم اللہ مُجریہا مُرسٰہا کہہ کر ڈرائیور کو جیپ اسٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا تھا۔
کوئی گھُٹے گھُٹے گلے سے رونے لگا تھا۔ کوئی بوڑھی سی آواز تھی۔
وہ آواز یں پھر آئیں جیسے روحیں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔
ہری بول ہری بول۔ ہری بول ہری بول۔ بولو بولو ہری ای ہری۔
ڈے کیئر
وہاں ہمیشہ میلہ لگارہتاتھا۔ کھوے سے کھوا چھلتا۔ خلقت یوں امڈی آتی تھی جیسے مفت کچھ بٹ رہاہو۔ لیکن مفت کچھ بٹتاہوتاتو کیاسب کے چہرے ایسے ہوتے ؟ سُتے ہوئے، متردد آنکھوں والے، موت کی پرچھائیاں جن پر رقص کرتی ہوتی تھیں۔ اپنی موت کی نہیں تو کسی عزیز کی موت کے اندیشے کی۔ کہیں امید وبیم کی دھوپ چھاؤں کے درمیان، توکہیں صرف اندھیروں کے درمیان۔
وہ نوجوان لڑکی اپنی خوبصورت آنکھوں میں ایک کربناک کیفیت لئے بڑے صبر کے ساتھ کرسی پربیٹھی اپنا نام پکارے جانے کاانتظار کررہی تھی۔ اس کے بغل والی کرسی پرکسی نے رومال ڈال کر اپنی جگہ مختص کردی تھی۔
’’میں یہاں بیٹھ جاؤں ؟‘‘ اچانک وہ سوال، جو گرچہ نہایت ملائمیت اورشائستگی کے ساتھ کیاگیا تھا اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ چونکنے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ اس کے ریشے ریشے میں ایک سُن ہوجانے والی کیفیت سمائی ہوئی تھی۔
سوال دوبارہ دوہرایاگیا۔ اس مرتبہ بڑی ہی نرمی کے ساتھ اس کے شانے پرہاتھ رکھ کر۔ اس لمس کی ایک زبان تھی، گونگی زبان جواس لڑکی کے وجود میں اترنے میں کامیاب رہی تھی۔
اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ سوال کرنے والی عورت عمر میں اس سے خاصی بڑی تھی۔ کوئی چالیس کے پیٹے میں۔ یاشاید کچھ اورزیادہ۔
’بیٹھ جائیے۔‘اس نے رسان سے کہا۔ ’یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیں گے تو اٹھ جائیے گا۔‘بڑی عورت رومال سرکاکر بیٹھ گئی۔ ہال ائرکنڈیشنڈتھالیکن بھیڑ کی وجہ سے اس کاتاثر کم ہوگیاتھا۔ پسینے اوردواؤں کی بو الگ رچ بس گئی تھی۔ عورت کو محسوس ہوتاتھا اس بڑے کمرے میں ایک اور بے نام مہک ہواکرتی ہے جو سب سے الگ ہوتی ہے۔ اتنی عمر گذارلینے کے باوجود اس نے پہلے کبھی ایسی مہک نہیں سونگھی تھی۔ دبے پاؤں آتی موت کی مہک۔ آج بھی ایک اسٹریچر سرکاکر دیوار سے لگایا ہواتھا۔اس پر پڑا ایک شخص گویا اپنی آخری سانسیں گن رہاتھا۔ اس کے جسم میں کئی دوائیں داخل کی جارہی تھیں۔ پاس ہی ایک عورت اسٹریچر کی پٹی پکڑے کھڑی تھی۔ دونوں بہت غریب، بے حد مسکین۔ یقیناً یہ مہک انکے پاس سے آرہی تھی۔ عورت جب جب اپنی باری پریہاں آئی تھی، اس طرح کوئی نہ کوئی اسٹریچر اسے ضروردکھائی دیا تھا۔ کبھی ادھرادھر پہنچایا جاتا۔ کبھی دیوار سے لگاکر کھڑا کیاہوااور اسے ہربار یہ خیال آیاتھا کہ ایسی حالت میں توآرام سے مرنے دیاجاتا تو بہترتھا۔ اتنی اذیت کے بدلے چند سانسیں دے کرکیاملتاہے ؟فضا میں موت کے قدموں کی چاپ یوں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی تھکاہوا دل آہستہ آہستہ کانوں میں آکر دھڑک رہاہو۔
گھٹن ناقابل برداشت تھی۔ رومال رکھ جانے والا بھی ابھی نہیں آیاتھا۔ دوسرے کی سیٹ پرقابض ہونے کے خفیف سے احساس جرم کے ساتھ وہ عورت وہیں بیٹھی تھی۔ ایک عدم تحفظ کااحساس بھی تھا۔ ابھی وہ آجائے گااوراسے اٹھنا پڑے گا۔ جیسے اس کے عزیز کانام پکارے جانے پر خوداسے بھی سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ ہم سب اپنی اپنی طلبی کے منتظرہیں۔ اس نے دلگرفتگی کے ساتھ سوچا…اندر اٹھتے سناٹے سے گھبراکروہ بغل میں بیٹھی لڑکی کی طرف مڑی۔
کون بیمار ہے ؟‘‘
’’میرے شوہر‘‘اس نے مختصر جواب دیا۔
’’تمہارے شوہر؟‘‘ بڑی عورت نے حیرت سے دوہرایا۔’’ تمہاری شادی ہوچکی ہے ؟ ذرانہیں لگتاکہ تم شادی شدہ ہو۔تمہارے شوہر بھی بالکل کم عمر ہوں گے۔‘‘اس کے لہجے میں دلی تاسف تھا۔ چچ چچ !‘
لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی۔ سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لرزی، جیسے گھنے بادلوں کے پیچھے سے بجلی کی خفیف سی روشنی کااحساس۔ وہ خاموش رہی۔ یہاں ہرشخص بول رہاتھا لیکن کسی کوکسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ دلوں میں سناٹا پسراپڑارہتاتھا بے کراں اورلامتناہی۔ بیک وقت موجود اس سناٹے اور شور کے درمیان ڈے کیئر وارڈ کے دروازے پر کھڑے باوردی گارڈکی آوازمائک پر گونجتی۔ وہ لوگوں کے نام پکارتاتھا۔کسی کے مریض کی کیموتھریپی مکمل ہوچکی ہوتی تو اس کے کاغذات لے کر اسے واپس لے جانا ہوتا۔ کسی کے لئے جگہ خالی ہوئی ہوتی تومریض کولے کر اندر پہونچانا ہوتا۔ کیموکے درمیان بھی کبھی ساتھ آئے نگراں کی ضرورت پڑجایاکرتی تھی۔ ذرا کی ذرا گارڈ کی کرخت آواز باقی آوازوں پرحاوی ہوجاتی، پل بھر کوسناٹا چھاجاتا۔پھر انتظار کررہے ہراساں لوگوں میں سے باری آجانے والا شخص ہڑبڑاکراٹھتا۔
روکیاکھاتُن…روکیاکھاتُن…۔مائک کھڑکھڑایا تھا۔
لمبی داڑھی اورملگجے کرتے والا ایک نہایت تھکا تھکا ساشخص چوکنا ہوکر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔حلئے بشرے سے آس پاس کے کسی دیہات سے آیاہوا لگتا تھا۔ ویسے تواس عظیم الشان شہر میں بھی اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ یہاں وہ بھی تھے جو سرسبز درختوں کے درمیان گھرے پرسکون، کشادہ اور خوبصورت بنگلوں میں رہتے تھے اوروہ بھی جو علی الصبح ٹھیلہ لے کران بنگلوں میں سبزیاں اور پھل پہنچایا کرتے تھے۔ وہ بھی جو کامن ویلتھ گیمزکے دوران عالیشان ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے۔ اوروہ بھی جنہوں نے سخت مشقت کرکے ان کے لئے شہر کو دلہن کی طرح سجایاتھا اورپھر نکال کرباہر کردیے گئے تھے کہ رہ جاتے تو دلہن کے چہرے پر برص کے داغ کی طرح ابھر آتے۔ اس لئے کسی کی صورت دیکھ کر کوئی کیاسمجھ پاتاکہ وہ کہاں رہ رہاہے۔ کسی گاؤں میں یا بڑے شہر کی جھونپڑپٹی میں۔
اعلان کے بعد گارڈ نے چند لمحوں کاتوقف کیااور اس کے بعدباہر آگیا۔اس نے مائک اپنے اسٹول پر چھوڑدیاتھا۔
’’روکیا کھاتُن کون ہے ؟‘‘بھیڑکے درمیان گھس کر اس نے زورسے آواز لگائی ’’جلدی کیجئے، آپ لوگ پکارنے پردھیان نہیں دیتے دوائی شروع ہونے میں دیر ہوتی ہے‘‘۔ گواس کی آواز تیز تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ نرم اورہمدرد۔
اسی ہسپتال کے دوسرے شعبوں میں وارڈ بوائے اورنرسیں اتنے نرم خونہیں تھے۔ ایک مرتبہ دواؤں اورپرہیز کی وضاحت کردینے پر بات سمجھ میں نہ آئے اورمریض دوبارہ پوچھ بیٹھے توخاصے ناراض ہوتے تھے۔ ’’ارے کیاہم صرف تمہارے لئے نوکری کررہے ہیں ؟اتنے لوگ اور جوانتظار کررہے ہیں ان کاکیا ؟‘‘ ایک مرتبہ ایک شخص کہہ بیٹھا ’’میڈم اتنی دیرتک ڈانٹنے سے اچھاتھا کہ ایک بار اورسمجھادیتیں ‘‘ نرس نے اسے خشمگیں نظروں سے گھورا اورآگے بڑھ گئی۔ وہ بے چارہ ایک ایک کوپکڑپکڑ کرپوچھنے لگا کہ کتنی بار دوا کھانی ہے اوردوبارہ انجکشن لینے کب آنا ہے۔ بہت دیربعد ایسا شخص مل سکا جوپڑھا لکھابھی تھا اور مہربان صفت بھی۔ ویسے کئی پڑھے لکھے ایک نظر ڈال کراس لئے بھی آگے بڑھ گئے تھے کہ کام کے دباؤ پرنسخہ لکھنے والے ڈاکٹروں کی گھسیٹی گئی جناتی تحریر پڑھ لینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اس شعبے کے ڈے کیئرکاعملہ نہایت نرم خواور خلیق تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہاں جوآیا ہے اس کا ٹکٹ کٹ چکاہے بس دوپاٹوں کے بیچ پس رہے چنے کے دانوں میں سے کوئی کوئی ہی بچ نکلے گا اورلوگ کہیں گے، ہاں بھائی جاکوراکھے سائیاں …سائیاں کورکھنا ہوتو اس مرض میں مبتلا ہی کیوں کریں۔
گود میں بڑی بڑی آنکھوں اورزرد چہرے والی تین چار برس کی لاغربچی کولئے وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ’’شاید ہمیں کو کہہ رہے ہیں۔ رقیہ خاتون کو بلا رہے ہیں ‘‘۔
’’ہاں چلئے جلدی کیجئے‘‘گارڈ نے بچی کی طرف پیار سے دیکھا۔۔اس شخص نے تیز تیز چلتے ہوئے بچی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی فائل سنبھالی۔ہڑ بڑائی ہوئی رفتار کے باوجود بچی کا منہ چوما۔پھر وہ بدبدایا۔
’’پتہ نہیں کیسے کیسے نام بولتے ہیں گارڈ جی۔ ہماری سمجھ میں ایک بار بھی نہیں آیا۔سسٹر ناراض ہوں گی ٹائم کھوٹا ہورہا ہے ان کا۔ ‘‘
’’کیسی چھوٹی سی، معصوم سی بچی ہے۔‘‘بڑی عمر والی عورت پھر بولی۔
کچھ لوگ دکھ میں خاموش رہتے ہیں کچھ بول بول کر جی ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عورت فطرتاً خاموش طبیعت تھی لیکن اب باتونی ہوگئی تھی۔اسے لگتا تھا خاموش رہی تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔
نوجوان لڑکی سر نیچا کئے بیٹھی تھی۔اس نے پھر آنکھیں اوپر اٹھائیں۔
’’میری بیٹی بھی اتنی ہی بڑی ہے‘‘اس کی آواز میں آنسوئوں کی کھنک تھی۔
’’ارے رے رے۔کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہو؟‘‘
’’ماں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ یہاں ان کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی تھی۔بچی رُل رہی تھی۔‘‘
ایسا لگا جیسے اجنبی دیار میں جہاں نفسی نفسی کاعالم تھا،ایک غیر متوقع ہمدرد کی موجودگی نے لڑکی کے ضبط کا باندھ توڑدیا تھا اور اس کی گونگی زبان بھی بول پڑی تھی۔
’’ایک اتنی ہی بڑی بچی کو میں نے آنکھ کے کینسر میں مبتلا دیکھا۔درد سے سر پٹک رہی تھی۔اس کی ماں ہاتھ مل مل کے رو رہی تھی۔اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی کہ ایک نرس وہیں دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور خود بھی رونے لگی۔‘‘بڑی عورت نے کہا۔
’’بس کیجئے۔یہاں اپنے دکھ کافی ہیں رونے کے لئے‘‘نوجوان عورت کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔
’’ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ سب نہیں سنانا چاہئے تھا۔‘‘بڑی عورت نے کہا اور خاموش ہوگئی۔
نوجوان لڑکی کو کچھ افسوس ہوا۔آخر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی بیمار ہے۔عمر میں اس سے بڑی بھی ہے۔اس سے اس طرح جھڑک کرنہیں بولنا چاہئے تھا۔جو وہ بتا رہی تھی اس طرح کے نظارے تو آنکھوں کے سامنے روز آتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی بدتمیزی کا کچھ تدارک کرنا چاہا۔بڑی نرمی سے پوچھا:
’اور آپ کس لئے آئی ہیں ؟کون بیمار ہے آپ کا؟‘
’ میرا گیارہ سال کا بیٹا۔کیمو چل رہی ہے اس کی‘۔
’اوہ!‘نوجوان لڑکی اندر سے ہل گئی۔ایک عورت کے لئے اولاد اس کے سہاگ سے بھی بڑی ہوجاتی ہے۔اسے اپنی بچی یاد آئی جسے وہ ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی کہ شوہر کی بیماری کی وجہ سے وہ نظر انداز ہورہی تھی۔ہمہ وقت شوہر کے ساتھ لگے رہنے اور اداس ودلگرفتہ ہونے کے باوجود ایک لمحے کو بھی بچی ذہن سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔
’آپ کے پتی؟‘اس نے بات جاری رکھنی چاہی۔
’’بچے کے ساتھ ہیں۔ ابھی باہر لے گئے ہیں۔ ہم لوگ سویرے سات بجے ہی آگئے تھے۔معلوم ہوا بارہ بجے کے بعد نمبر آئے گا۔‘‘
دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی نے پیر پسار دئے۔ہال آوازوں سے گونجا کیا۔
پھر بڑی عورت نے ہی خاموشی توڑی۔
’’وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔بڑی منت مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔دوا کر کرکے ہار گئے تھے۔سارے پیر فقیر سنت اولیا بھی منا لئے۔بالکل مایوس ہو چکے تھے تبھی اچانک بارہ برس بعداوپر والے نے ہماری گود بھر دی۔مگر کیوں ؟ کس لئے؟شاید یہ جتانے کے لئے کہ اس کی مرضی نہ ہو تو اس سے ضِد کرکے کچھ نہیں مانگنا چاہئے۔بے اولاد ہونے کا دُکھ تو اس دُکھ سے بہتر تھا۔‘‘
نوجوان عورت پھر اندر سے ہل گئی۔ایک اولاد،وہ بھی شادی کے بارہ برس بعد اللہ آمین کا بچہ۔
بڑی عورت خاموش نہیں ہوئی تھی۔اس کی بات جاری تھی۔
’’ہم سخت وجیٹیرین تھے۔انڈا تک ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ڈاکٹر نے کہا لڑکے کو پروٹین زیادہ دینے ہیں۔ ہم نے اسے نان ویج کھلانا شروع کیا۔ایک آدھ بار ہوٹل سے لائے۔لیکن پھر سوچا ڈاکٹر نے انفکشن سے خبردار کیا ہے۔اس لئے ہم نے گھر ہی میں بنانا شروع کردیا۔اولاد کے لئے ہم نے دھرم ا ٹھا کے طاق پر رکھ دیا۔اب ہمارے گھر کے اندر انڈا مرغا سب بن رہا ہے۔کوکری کلاس جوائین کرکے یہ سب بنانا سیکھا۔طرح طرح کی ڈشیں بناتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے تھالی پروستے ہیں۔ ہاتھ سے نوالہ بنا کر منہ میں دیتے ہیں۔ شوق سے کھاتا ہے۔جتنے دن بھی اس کی سیوا کا سکھ پالیں۔ ‘‘اس کی آواز میں اب کوئی تاثر نہیں تھا۔اس کا غم شدت کی اس انتہا کو پہنچ گیا تھا جہاں سب کچھ شونیہ میں گم ہو جاتا ہے۔
کھرکھراتی ہوئی آواز میں تبھی اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا’’وہ رہے باپ بیٹا۔ سوا بارہ بج بھی رہے ہیں۔ اب نمبر ضرور آجائے گا۔میرا بچہ،میرا غریب معصوم بچہ۔ہر تین ہفتہ پر تکلیف اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ففٹی ففٹی چانس ہے۔‘‘
نوجوان عورت نے اس طرف دیکھا۔دیکھنے میں ذرا نہیں لگ رہا تھا کہ بچہ بلڈ کینسر کا مریض ہے۔گورا،چٹاّ،مزے کے ڈیل ڈول والا۔بس آنکھوں میں زردی کھنڈی ہوئی تھی اور سرگھٹا ہوا تھا۔کیمو تھیریپی کے ردعمل سے بال گر جانے پر بہت سی عورتوں تک نے سر منڈوا کر اسکارف باندھے ہوئے تھے۔
نوجوان عورت نے گلے میں کچھ پھنستا ہوا محسوس کیا اور پلکیں جھپکا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
اسی وقت مائک کھڑکھڑایا اور گارڈ نے کچھ کاغذات پر نظر دوڑاتے ہوئے آواز لگائی ’’اکھیل، اکیِل…اوہ اکِل…اکھیل کے گھر والے آجائیں۔ ‘‘
بڑی عورت بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی ’’آجائو بیٹا تمہارا نمبر آگیا ہے۔‘‘
نوجوان عورت بھی اسی اضطراری کیفیت کے تحت اٹھ گئی تھی۔
’’نہیں یہ عقیل کے لئے کہہ رہا ہے،میرے شوہر کے لئے۔وہ بیڈ پر ہیں۔ دوا چڑھ رہی ہے۔کچھ چاہئے ہوگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔‘‘
گارڈ نے اس مرتبہ ہکلاہٹ پر قابو پاکر نام ذرا زور دے کر دوہرایا…’’اکھیِل کے ساتھ والے آجائیں …‘‘
’’نہیں نہیں ہمارا نمبر آگیا ہے۔‘‘بڑی عورت تیزی سے چلتی ہوئی بولی۔
اکھیِل پانڈے یا عقیل احمد…؟دونوں خواتین تیز تیز قدموں سے گارڈ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔
آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دہلی کے بی آر امبیدکر کینسر انسٹی چیوٹ کے ڈے کئیر سیکشن میں ہمہ ہمی جاری تھی
گڑیا
وہ گھر سے چلی توجھٹپٹاہوچلاتھا۔ٹرین رات کے نوبجے تھی جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا تھا۔ ٹرین کیاہوتی ہے یہ وہ جانتی تھی۔ ایک دوریل گاڑیاں اس کے گاؤں کے کنارے کنارے گنّے اور ارہر کے کھیتوں کے پاس سے گزراکرتی تھیں۔ وہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں اس پراس نے کبھی غورکرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ کبھی کسی ٹرین سے سفر کرنے کاموقعہ بھی نہیں ملا تھا۔ اللہ میاں کے پچھواڑے والے اس گاؤں میں اس کاکچا‘ پھوس کے چھپر والاگھر ایسی جگہ تھا جہاں سے بس اسٹینڈ تک جانے کے لئے بھی کوئی سواری نہیں تھی۔ کچھ دور پیدل چلنا تھا پھربس پرچڑھ کروہاں پہونچنا تھا جہاں سے ٹرین پکڑی جاسکتی تھی وہ بس پرچڑھی تھی اوربس اڈہ گھرسے اتنا قریب تھا کہ وہاں کئی مرتبہ یوں بھی جانکلتی تھی وہاں ایک بڑا سا تالاب تھا جس میں لوگ بھینسوں کونہلاتے اور پاس کھڑے تاڑ کے درختوں سے تاڑی اتارتے۔ بھینسیں اوربطخیں اورسور ادھر ادھر منہ مارتے رہتے۔ درمیان میں کٹ کٹ کٹاک کرتی مرغیاں گھس آتیں بکریاں دراندازی کرتیں۔ کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ اسے کبھی یہ نہیں محسوس ہواتھا کہ اس کی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ توبس وہاں تھیں اورہمیشہ سے تھیں جیسے کھیت کھلیان، اڑوس پڑوس، ہواپانی،اماں ابا، بھائی بہن، نشیٹری ماموں۔ آج اچانک وہ سب کے سب بڑے اہم ہوگئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ بدصورت سوربھی جن کے بارے میں مولی ساب کاکہناتھا کہ ان پرنظرپڑجائے تو لاحول پڑھ لیاکرو۔ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت سب سے پہلا خیال اسے یہ آیاتھا کہ یہ سب وہاں ہوں گے یانہیں جہاں وہ جارہی تھی یایوں کہاجائے کہ لے جائی جارہی تھی۔ تالاب توتالاب اس وقت اماں بھی بڑی اہم ہوگئی تھی جس کے بارے میں اس نے کئی مرتبہ سوچاتھا کہ مرکیوں نہیں جاتی۔ ہروقت ڈانٹتی رہتی ہے۔کھاناکم ہوتوپہلے بیٹوں کو کھلادیتی ہے۔ آج سے پہلے اس محبت کاکبھی احساس نہیں ہواتھا جواسے اماں سے تھی۔ اماں اگر سارا کھانابٹیوں کوکھلادیتی تھی تواس دن خود بھی تونہیں کھاتی تھی اور جب اماں نے چلتے وقت اس کے سرپر ہاتھ رکھا اس میں وہ کون سی کیفیت تھی جس کی وجہ سے اسے اپنے ننھے سے دل میں اندرہی اندر آنسو امنڈتے محسوس ہوئے اور ایسالگا کہ اماں تو بہت ہی پیاری ہے۔
دونوں چھوٹے بھائی اورایک بہن آکر اغل بغل کھڑے ہوگئے۔ شاید جھلنگے پلنگ پر پڑی چھ مہینے کی بہن نے بھی کروٹ بدلی اور کالا دھاگہ بندھی سوکھی ٹانگ سے ہوا میں لات چلائی۔ اماں کہتی تھی کالا دھاگہ باندھنے سے نظرنہیں لگتی۔ اس سوکھی کالی‘ زورسے رونے کی بھی طاقت نہ رکھنے والی بچی کو کس کی نظرلگنے والی تھی؟
ویسے وہ دونوں جواس کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتے چل رہے تھے اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کے پاس سے خوشبو بھی آرہی تھی۔ ایسی خوشبو مولسری کے درخت کے نیچے آیا کرتی تھی یاجب کچے احاطے میں لگی رات کی رانی مہکتی یا ہارسنگھارنے ہنس ہنس کے پھول جھاڑے ہوتے۔ انسانوں کے پاس سے ایسی خوشبوئیں کہاں آتی تھیں۔ کیا ان خوشبودار لوگوں کے گھر رات کی رانی مہکتی ہوگی ؟ کیاوہاں مولسری کادرخت ہوگا؟ کیاہار سنگھار وہاں بھی ہنس ہنس کراپنے ننھے ننھے ستاروں جیسے سفیدپھول جھاڑتا ہوگا جن کی نازک ڈنڈیاں بطخ کی چونچ جیسے گہرے نارنجی رنگ کی ہوتی ہیں کیاوہاں بھی تالاب ہوگا اور اس کے کنارے وہ گندے بدہئیت سورہوں گے جن کی وجہ سے ابا کے اپنے بچوں کو غصے میں سور کابچہ کہنے پر اسے بے حد غصہ آتا۔ (گالیاں دیتے ابااسے بہت برے لگاکرتے تھے لیکن ابھی خاموش، کنارے کھڑے اباپراسے بڑا ترس آیا) یہ چشم زدن میں زندگیاں یوں کیسے بدل جایاکرتی ہیں (ایسا سوچنے کے لئے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے لیکن سوچ تو الفاظ کی پابندنہیں ہوتی ورنہ گونگے بہرے کبھی کچھ نہ سوچ پاتے ) اس نے جاتے جاتے پلٹ کرایک نظراپنی محبوب بکری پر ڈالی جو کھونٹے سے بندھی بیٹھی مزے سے جگالی کررہی تھی۔ دونوں بچے پاس ہی پھدک رہے تھے اوربکری کے دودھ سے بھرے تھن زمین پرلوٹ رہے تھے اس کاجی چاہا ایک بار پاس جاکر اس کے گلے میں بانہیں ڈال کر اسے الوداع کہہ کر آئے۔
بس چلی تو سارا کچھ پیچھے چھوٹنے لگا۔ تاڑی پی کر اماں کی اکلوتی چیز چاندی کی پائل، چرانے والے ماموں اورہوا پی کر نشہ کرنے والے جھومتے تاڑکے درخت، کھیت کھلیان، تالاب، ڈھٹائی سے راستے میں کھڑی گائیں ‘ امرتی ساؤ کی دوکان پرجلتی ڈھبری اوربلاوجہ بھونکتے کتے۔ اورجب ٹرین چلی تو جوپیچھے چھوٹ رہاتھا اس کے چھوٹنے کی رفتار اورتیز ہوگئی۔ ہاں چاند اس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا اور وہ ستارہ بھی جو اس کے گھر کے ٹھیک اوپر سے جھانکا کرتاتھا۔ کیایہ اس کے ساتھ ساتھ پٹنہ شہر تک جائیں گے ؟ ان لوگوں کے گھر سے بھی دکھائی دیں گے؟
اماں نے کہاتھا ان لوگوں کوبھیا۔ بھابھی کہنا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا پھراس کابستر بچھادیا۔ٹرین الگ جھولا جھلارہی تھی۔ پہلے اسے لگ رہاتھا آج کی رات بہت بھاری ہے لیکن ایسی نیندآئی کہ صبح جھنجھوڑکر جگایا گیا۔
اسٹیشن، گھر، گردوپیش دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تلاؤ کی مچھّی کوکسی نے اچھال کر گنگا میں ڈال دیا تھا۔
گھرمیں ایک بڑی شفیق برزگ عورت تھیں۔ جنہیں لوگ اماں کہتے تھے۔ یہ دونوں تھے جو اسے لائے تھے اماں کے بیٹا۔ بہو،دوچھوٹے لڑکے تھے۔ ایک پانچ برس کا اوردوسرا کوئی ڈھائی تین سال کا۔ بچے ایسے خوبصورت، صحتمند اورخوش وخرم لیکن اس کے ذخیرئہ الفاظ میں صحتمند اور خوش وخرم جیسے الفاظ تھے ہی نہیں۔
سب لوگ روز نہادھوکر کپڑے بدلا کرتے تھے۔ اتنے کپڑے؟ اسے بھی توایک ساتھ دوجوڑے دیے گئے اورایک جوڑکپڑے بھابھی یہاں سے لے کر بھی گئی تھیں جواسے پہنا کرلائی تھیں۔ اسکاکثیف، پرانا جوڑا وہیں چھوڑدیاگیاتھا۔ نئے چپل، بالوں کے لئے ربن۔ اسے ایک چھوٹا بکس دیاگیا۔ اس میں سارا سامان تھا۔ یہ ہمارا ہے ؟ ہمارا ؟وہ ہکلائی تھی۔ بہت دیرلگاکر اسے یقین ہواکہ یہ چیزیں اسی کی ہیں۔
سب اس کے ساتھ اچھابرتاؤ کررہے تھے۔ بس موٹی ملازمہ جو صبح شام آکر جھاڑو بہارو کرتی اور کھانا پکاتی، کچھ ٹیڑھی ٹیڑھی سی رہاکرتی تھی۔ پہلے دن بھی اس نے کہاتھا ’’ اے چھوکڑی، خالی بیل جیسی آنکھوں سے تاکے ہے کہ کچھ کام دھام بھی جانے ہے‘‘ اس پر ان بزرگ خاتون نے تنبیہ کی تھی۔
’’ سیکھ لے گی سیکھ لے گی۔ اورکام ہے بھی کیا۔ دونوں بچوں کوہی توسنبھالنا ہے ‘‘۔
کئی دن گزرجانے کے بعد بھی وہ اس سارے کارخانے کوپھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں دیکھتی رہتی تھی جیسے ان میں سارے جہاں کی حیرت سمٹ آئی ہو۔ ایک دن وہاں ان بچوں کے ماموں آئے۔ ان کوبھی وہ دیرتک گھورتی رہی۔ ماموں کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں عمدہ پینٹ شرٹ میں ملبوس۔ ہنس مکھ، بچوں کے لئے بہت سے چاکلیٹ لانے والے ماموں کیااپنی بہن کازیور چرائیں گے؟
’’ارے یہ کہاں سے مل گئی۔ ‘‘ انہوں نے بزرگ خاتون سے کہا۔ انہیں وہ اماں کہہ رہے تھے۔
’’ کشن گنج والی کے غریب رشتہ داروں کی لڑکی ہے۔ ان کے یہاں ضرورت نہیں تھی۔ یہاں رکھوادیا۔ ‘‘
’’ ارے توایک ہمیں بھی دلوادیں۔ ‘‘
’’لوبھلا۔ بازار میں بک رہی ہیں کیا۔‘‘
’’اس کی کوئی بہن نہیں ہے ؟‘‘
’’ہے تولیکن ماں باپ اب دیں گے نہیں۔ لڑکی کوباہر بھیجنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کشن گنج والی پرانہیں پورا بھروسہ تھا اس لئے بھیج دیا ۔ ‘‘
’’اماں، آپ ہماراخیال نہیں کررہیں۔ ‘‘
’’میاں پہلے اپناخیال۔ اس عمر میں دوبچے تنہا ہم پال رہے تھے۔ دلہن بیگم دن بھرنوکری پہ۔ اپنے بچوں کوپال پوس کے بڑا کردیاتھا۔ اب بڑھاپا خراب۔ ‘‘
’’ارے تم اپنی بہن کوبلاسکتی ہو؟ ‘‘انہوں نے براہ راست اس سے سوال کیا۔
وہ تکتی رہی
’’ایسے ہی تاکے ہے ٹکرٹکر۔ کوئی کام تھوڑی کرے ہے۔ خالی کھائے کو آئی ہے۔ کھاہے ڈبرابھر کے‘‘ موٹی بوا مونہہ ہی مونہہ میں بڑبڑائیں۔
’’بوا ایسے مت کہئے۔‘‘ وہ جواماں کہلاتی تھیں ان کے کان بڑے تیز تھے۔ ’’ بچوں کویہی دیکھے گی ابھی تو ہم اسے کام سکھارہے ہیں۔ رہا کھانا توابھی بھوکی ہے جب نیت سیر ہوجائے گی توہم لوگوں جیسی ہوجائے گی۔‘‘ اس کی تربیت شروع ہوچکی تھی۔
بڑابچہ اسکول جاتاتھا۔ (وہ خود کبھی اسکول نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد جوبھائی تھا وہ کبھی مسجد میں مولوی صاحب کے مدرسے جانکلتاتھا۔ یہاں پانچ برس کا بچہ اسکول جاتاہے وہ بھی روزانہ بلاناغہ …) یا مظہرالعجائب! (مگراسے یامظہرالعجائب کہنا نہیں آتاتھا۔)اس کو اسکول کیلئے تیار کرنا، بیگ میں ٹفن کاڈبہ اور پانی کی بوتل ڈالنا، جوتے پالش کرنا اور اس کے جانے کے بعد چھوٹے کاخیال رکھنا اس کے ابتدائی سبق تھے۔ چھوٹے کوبوتل میں دودھ بھرکردینا تھا جو وہ دن میں تین چار مرتبہ پیتا تھا۔ جتنی مرتبہ و ہ بوتل میں دودھ ڈالتی اتنی مرتبہ صابن سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ گھر پر تو وہ اُپلے پاتھ کر بھی صابن سے ہاتھ نہیں دھوتی تھی۔
ان بچوں کے پاس ایک بڑی ٹوکری بھرکر کھلونے تھے۔ ان کے باوجود ہفتے میں ایک آدھ نیاکھلونا آہی جاتا۔ کبھی ماں باپ میں سے کوئی لے آتا، کبھی وہ ساتھ گھومنے نکلتے توبچے خود فرمائش کرکے لے لیتے۔ وہ زیادہ ترگاڑیاں لے کرآتے۔ کار،ٹرک، بس، پولس کار، بائیک پھر بندوقیں، ریوالور، ان کی نقلی گولیاں، پٹری پرگول گول گھومتی ٹرین فٹ بال گیندیں لڑکے تھے نااس لئے ان کے کھلونوں میں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ ایک بار اس نے میلے میں پلاسٹک کی ایک گڑیا خریدنے کی ضد کی تھی۔ ابانے اسے بھدی سی مٹی کی گڑیا لے دی۔ پلاسٹک کی گڑیا بہت مہنگی تھی۔ مٹی کی گڑیا سے کھیلنے میں اتنا مزہ نہیں آیااوربھیاسے لڑائی ہوئی توتیسرے دن اس نے گڑیا توڑبھی دی۔
لیکن ایک دن لڑکوں کے اس گھر میں بھی اس کی حیران آنکھوں نے گڑیا ڈھونڈنکالی۔ بہت بڑی تقریباً نوزائیدہ انسانی بچے کے سائزکی، موٹی، گدبدی، نیلی آنکھوں اورسنہرے بالوں والی اس نے سچ مچ کی فراک پہن رکھی تھی اور اس کے جوتے بھی بالکل اصلی تھے بالوں میں سرخ رنگ کاربن بند ھا ہواتھا۔ ابھی اس گھر میں اور کیاکیا دیکھناباقی ہے۔ایسی بھی گڑیاں ہوتی ہیں ؟ اتنی حسین، ایسی کہ معلوم ہوزندہ ہیں، بس ابھی بول اٹھیں گی۔ اس کادل اسے گود میں اٹھانے کو مچل گیا۔
اب اسے بھابھی نے اپنے کمرے میں جھاڑپونچھ کاکام بھی سونپ دیاتھا۔ کچھ دن سے موٹی ملازمہ کام بڑھ جانے کی شکایت کررہی تھی۔ وہ پہلے دن کمرے میں داخل ہوئی توسب سے پہلے نظر گڑیا پرہی پڑی شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک اسے تکتی رہی توبھابھی نے بتایا کہ یہ ان کی گڑیا تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد وہ اسے اپنے گھر سے لے آئی تھیں۔ حیرت سے عموماً اس کی زبان گنگ رہتی تھی اورویسے بھی وہ ایک خاموش طبعیت لڑکی تھی۔ حالانکہ بھابھی ابھی نوجوان تھیں۔ بالکل لڑکی جیسی لگتی تھیں لیکن شادی شدہ تھیں ان کے دوبچے تھے کیاان کی عمر کی عورتیں گڑیا کھیلتی ہیں جووہ اپنی گڑیااٹھالائی تھیں ؟ ایسی گڑیا ملتی کہاں ہے اورکتنے پیسوں میں ملتی ہے ؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن کی تہوں سے اٹھ اٹھ کرواپس انہیں میں دفن ہوتے رہے ہاں اس گڑیا کوچھونے، اس سے کھیلنے کی خواہش جنون کی حدتک سرپرسوار ہونے لگی۔
انہیں دنوں ایک دوپہرمیں اماں حسب معمول اپنے کمرے میں لیٹنے جاچکی تھیں۔ بھیا بھابھی اپنے اپنے دفتر میں تھے اوروہ دونوں بچوں کولے ان کے کمرے میں انہیں سلانے کی کوشش کررہی تھی جبکہ دونوں میں سے کوئی سونے پرآمادہ نہیں تھا۔
’’اے‘ ہمارے ساتھ کھیلونا‘‘
’’بابو گڑیا کھیلیں گے ؟‘‘
’’ہم لڑکی نہیں ہیں۔ گڑیاسے تولڑکیاں کھیلتی ہیں۔ چورسپاہی کھیلتے ہیں۔ ‘‘
’’ہمارے ساتھ کھیلئے نا۔ ہم تولڑکی ہیں۔ لائیں ؟ ‘‘ اسے بھابھی کے کمرے میں داخلہ مل چکاتھا۔
اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھاہوا اخروٹ کی لکڑی کاسبک اسٹول کھسکا یا اور اس پر چڑھ کر گڑیا اتارلی۔ گود میں لیا تومحسوس ہوا جیسے جنم جنم کی پیاس مٹ گئی ہو۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی۔ ربن کھول کرپھرسے باندھا، فراک دوبارہ پہنائی۔ لڑکے نے کبھی گڑیا نہیں کھیلی تھی لیکن ابھی اسے بھی بڑا مزہ آیا۔ چھوٹا لڑکااپنے لکڑی کے گھوڑے پربیٹھاجھول رہاتھا۔ بڑے نے گڑیا اسے دی۔ لواسے اپنے گھوڑے پر بیٹھالو۔ سیر کراکے لے آتے ہیں۔
تینوں کھلکھلاکر ہنسے۔ یہاں آنے کے بعدپہلی مرتبہ وہ اس طرح دل کی گہرائیوں سے کھلکھلاکرہنسی تھی۔ ایسی ہنسی تواس کے اپنے گھر میں بھی شایدہی گونجتی ہو۔
’’اب رکھ دو۔ بڑے نے کہا۔ ممی دیکھیں گی توڈانٹیں گی۔‘‘
لیکن اس دن اس کی زندگی میں ایک نیاورق کھلاتھا۔ گڑیا اکثر دوپہر میں خاموشی سے اترکرنیچے آجاتی اورتینوں مل کر گڑیا سے کھیلتے۔ اس نے اسے دونوں بچوں کی چھوٹی بہن بنادیاتھا۔ چھوٹے کے نہ سہی لیکن بڑے بچے کے ذہن میں بہن کاتصور تھا۔ گڑیا موٹرمیں سوار ہوتی۔ گھوڑے پرساتھ بیٹھ کر گھومنے نکلتی۔ ایک دن اس کی فراک اور ربن دھوکر سکھائے گئے۔ ادھر لڑکی کو بچوں کے کپڑوں پراستری کرنا سکھایاگیاتھا۔ اس نے استری لگائی اوردونوں چیزیں پریس کیں۔ انہیں نئے سرے سے پہنایاگیا۔ربن کودوسرے اندازمیں باندھا گیا اور پھر واپس رکھنے سے پہلے، پہلے جیسا کردیاگیا۔یہ گڑیا ہم اپنی بہن کودکھاتے۔ وہ بھی اس سے کھیلتی۔ میری بیچاری ننھی بہن۔ آٹھ سال کی ہوگئی اسے کوئی گڑیا نہیں ملی۔ اسے دیکھے گی توکیسی خوش ہوگی۔اس نے سوچا۔ اب اس کی آنکھوں کی حیرانی کم ہونے لگی تھی لیکن دل میں خواہشات کاطوفان اٹھنے لگاتھا۔ آج ان لوگوں نے اسکول اسکول کھیلاتھا۔ یہ آئیڈیا بڑے لڑکے کاتھا۔ وہ ٹیچر بنا۔ لڑکی اورگڑیا اسٹوڈنٹ۔ تھوڑی دیر کوچھوٹا لڑکابھی اپناہیلی کاپٹر اڑانا بھول کر’کلاس ‘میں آبیٹھا تھا۔ ان لڑکوں کے پاس سچ مچ کابورڈ تھا۔ کافی بڑا۔ لیکن وہ سیاہ نہیں بلکہ سفید رنگ کاتھا۔ اس پرلکھنے کا خاص قلم تھا جو خوب موٹے حروف لکھتا۔ جب چاہو صاف کردو اوردوسرا کچھ لکھ لو یاتصویر بنالو۔ لڑکے کے پاس رنگین تصویروں والی بہت ہی خوبصورت کتابیں تھیں۔ اب تو ایک چمکیلی سی تصویر وں والی کتاب چھوٹے بچے کے لئے بھی آگئی تھی۔ وہ اب ساڑھے تین سال کاہورہاتھا۔ اوراسے اسکول میں ڈالنے کی بات ہورہی تھی وہ کتاب بڑی لبھاؤنی تھی۔ اس کابھائی مدرسے میں جو کتاب پڑھتاتھا وہ توشکل سے ہی ایسی لگتی تھی کہ پڑھنے سے انسان بھاگے۔ بس کالے کالے حروف ملگجاکاغذ۔ ہاتھ لگاؤ تو پھٹے۔ بابوجس کتاب سے ٹیچربن کراے بی سی ڈی پڑھارہے تھے وہ اگر بھیا کوملتی تو پڑھنے سے نہ بھاگتا۔
یہاں اماں نے اس کے لئے یسرناالقرآن منگادیا تھا۔ شام کو تھوڑی دیر بٹھاکر پڑھاتی تھیں۔ اس کاجی چاہتا ان تصویروں والی کتابوں سے بھی پڑھے اس لئے بابو نے جواسکول والا کھیل شروع کیاتواسے بہت ہی اچھالگا۔
’’ کہتے ہیں اچھانوکر بھی قسمت سے ملتاہے ‘‘ ایک دن اماں کے پاس سے وہ پڑھ کرہٹی تو وہ کسی سے کہہ رہی تھیں۔ شاید کوئی ملنے والی آنکلی تھیں۔ ’’ یہ لڑکی بس اللہ کی بھیجی آگئی۔ دونوں بچوں کوسنبھال لیتی ہے۔ بڑا آرام ہوگیاہے۔ اصل گھر میں سب سے بڑی تھی۔ کوئی نو۔ دس برس کی۔ اس کے بعد ان کی اماں کے چارچنیگی پوٹے۔ انہیں یہی سنبھالتی تھی۔ بس یہاں کے طور طریقے سیکھنے تھے۔ ہے ذہین۔ جلدی سیکھ لئے۔ ‘‘
اب کیانوکروں کوبھی نظر لگتی ہے۔ لے بھلاہو۔ کل ہی تواماں نے یہ بات کہی تھی یاشاید پرسوں اور آج صبح وہ گھرسے غائب پائی گئی۔
لوگ ایسے پریشان ہوئے کہ چہرے پرہوائیاں اڑنے لگیں۔ پرائی لڑکی۔ اورآج کل جوحال ہے نہ پانچ برس کی محفوظ نہ پچاس کی۔ گھرمیں ہڑکمپ مچ گیا۔
’’ اجی، لڑکی سے پہلے سامان تودیکھئے۔ ہم پہلے ہی نہ کہتے تھے۔ بیل جیسے دیدوں سے ہرچیز تاکے تھی۔ رات دلہن شادی سے آکر زیور اتارکرباہرہی رکھِّن ہیں۔ ‘‘ موٹی ملازمہ نے کہا۔ کوئی لگارہاہوگا ساتھ۔ بھابھی نے جلدی سے سنگارمیز کی دراز کھولی۔ وہ جب جھمکے اتاررہی تھیں تو وہ پاس کھڑی ٹکرٹکر مونہہ دیکھ رہی تھی۔
جھمکے وہیں تھے۔ سونے کی چوڑیاں بھی۔
دلہن تم نے پرسوں بینک سے پیسہ نکالاتھا۔ لاپرواہ ہو۔ کہاں رکھاتھا ؟ اماں بھی بول پڑیں۔
بھابھی نے جلدی سے بیگ ٹٹولا۔ پانچ پانچ سوکے نوٹوں کی گڈّیاں۔ روپے گنے۔ پورے تھے۔ اسے کپڑے رکھنے کے لئے جواٹیچی دی گئی تھی وہ وہیں تھی۔اس میں کپڑے بھی تھے۔ تب ؟
’’تب کون چیز ؟ کسی کے ساتھ نکل گئی ہے۔‘‘ ملازمہ نے کہا
’’اے ہے بُوا! خداسے ڈرو۔ دس ایک سال کی بچی۔ اماں نے کہا
’’اجی آج کل ٹی وی دیکھ دیکھ کے دس برس میں پوری عورت ہوجاں ہیں ‘‘
بوانے جواب دیا۔
میاں بیوی دونوں نے چھٹی لی۔ پولیس میں رپورٹ کریں توچائلڈ لیبر والے پکڑیں گے۔ خیراس کی نوبت آئی توکہہ دیاجائے گا کہ غریب رشتہ دارہے۔ ماں باپ نے یہاں پڑھانے کے لئے بھیجا ہے۔ مصیبت کردی لڑکی نے۔ اماں بہت لاڈکرتی تھیں۔ سب سے زیادہ آرام انہیں کوتھا۔ ڈرتی تھیں اگردل نہ لگا یا ناآسودہ رہی توچل دے گی۔ اب بھگتیں بلکہ سب کو بھگتوائیں۔ گاڑی لے کر نکلے۔ کیاپتہ ٹرین یا بس سے کہیں نکل گئی ہوتو کیاحشرہوگا۔ گھر پہنچ گئی توخیر، نہ پہنچی تواس کے ماں باپ کوکیامنہ دکھائیں گے۔ غریب بے چارے۔ بھروسے پرلڑکی سونپی تھی۔ چلتے وقت رخصت کرنے کو کھڑی ماں نے میلے کچیلے آنچل سے نہ جانے کن خاموش آنسوؤں کوپونچھا تھا۔
سارے دن کی تگ ودو کے بعد اسٹیشن پربیٹھی ملی۔ پھٹی پھٹی حیران آنکھوں کی حیرانی بکھیرتی، آتی جاتی گاڑیوں کودیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتی کہ کون سی گاڑی اس کے گاؤں جائے گی۔ ہونٹوں پرپپڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ گالوں پرآنسوخشک ہوچکے تھے۔ بغل میں گڑیا دبی ہوئی تھی اور اے بی سی ڈی والی پرائمر۔
٭٭

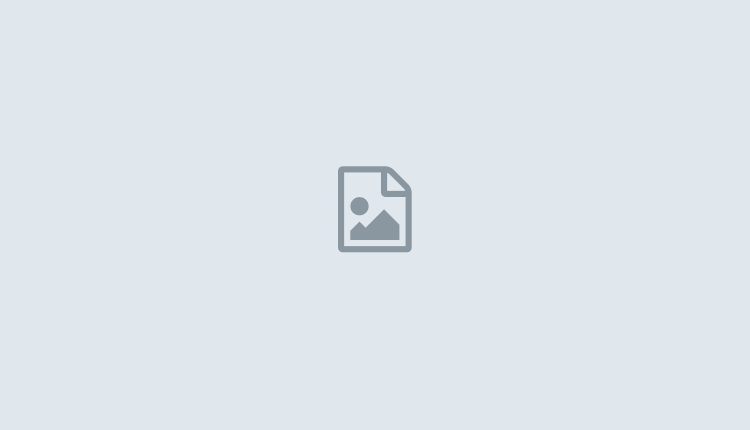
تبصرے بند ہیں۔