زبان کو دفنانا در اصل تہذیب کی موت ہے
پروفیسر صغیر افراہیم
اردوکی زبوں حالی کے تعلق سے اکثر مضامین، اداریے، کالم شائع ہوتے رہتے ہیں جو ہماری بے حسی پر تازیانے کاکام کرتے ہیں۔ ابھی ایسا ہی ایک کالم نظروں سے گزرا جس نے احساس دلایا کہ ’’اردو کے قاتل ہم‘‘ ہیں۔ اس موضوع پر لکھے جانے والے اکثر مضامین کی پیش کش کاانداز براہِ راست ذہن کوجھنجھوڑنے والا ہوتاہے۔ ان میں موجودہ منظر نامے کو پیش کرتے ہوئے اردو زبان کے تعلق سے کچھ ایسے چُبھتے ہوئے سوالات اُٹھائے جاتے ہیں جو غور وفکر پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم اگر ٹھہر کر ماضی اور حال کے پیش نظر روشن آنکھوں کے دریچوں سے، گزرے ہوئے دور پر نظر ڈالیں توواضح ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کے اخیر میں جب داغؔ دہلوی نے یہ کہا کہ ’’سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے‘‘ توسب نے تائید کی، کہیں سے کوئی مخالفت کی صدا نہیں اُٹھی۔ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں اردو کا ہر دبستان اپنی کج کُلاہی پر رشک کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن بٹوارے نے ہمارے دبستانوں خصوصاً شمالی ہندوستان میں اودھ، رامپور، ٹونک، بھوپال، دہلی کی آن بان شان کو تتربتر کردیا۔ مکان ومکین دونوں متاثر ہوئے۔ احساس برتری اور احساس کمتری کی ملی جلی شکل نے شخصیت کو اپنے خول میں سمٹنے یا پھر نقل مکانی پر مجبور کیا۔ اردو کے اِس خاص علاقے سے دور، اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہونی شروع ہوئیں مگر جائے پیدائش کو زک پہنچتی گئی۔ اعداد وشمار کے نتائج کو دیکھتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں دل ودماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ’’صرف اڑسٹھ سال میں ہمارا یہ حال ہوگیا کہ ہم نے اردو کے گھر میں اردو کو یتیم ویسیر بناڈالا‘‘۔ آخر کیوں ؟ جس کی تعمیر میں بغیر رنگ ونسل، ذات ومذہب کی تخصیص وتمیز کے صدیاں صرف ہوئی ہوں، اُس پر اُسی کے علاقے میں اتنی تیزی سے تنزلی آئی ہو، یہ بھی تسلیم کرنے کودل تیار نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمود طاری ہوا لیکن جمود بھی کیوں طاری ہوا؟ حیران کن سوال ہے۔ تخلیق کاروں نے اس کی نہایت موثر اور فن کارانہ روداد رقم کی ہے اور بالواسطہ طور پر یہ احساس دلایا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے کسی بھی اہم عہد کا مطالعہ کریں تو ہر دور کی اپنی خصوصیات ہیں جنھوں نے عالمی سطح پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں مگر مغلیہ عہد کی یہ بڑی خوبی قرار پائی ہے کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ملی جلی تہذیب کی پائیدار بنیاد پڑی۔ گنگا جمنی تہذیب کے طور پر زبانِ اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ یکے بعد دیگرے گزرتے ہوئے قافلے، منظر، پس منظر اور پیش منظر سے متعارف کراتے ہیں۔ ایسے قافلوں کی ’’آخری سواریاں ‘‘ محض ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں کرتی ہیں بلکہ حسین یادوں کے توسط سے غوروفکر کی مثبت راہوں کوروشن کرتی ہیں۔ مغلیہ دور کی شان وشوکت کے اگر ڈیڑھ سوسال قرار پاتے ہیں تو اُس کے زوال میں بھی اتنا ہی عرصہ لگا ہے مگر ’اردو‘ کسی کی جاگیر نہیں، سلطنت نہیں، مشترکہ تہذیب کی علمبردارہے، جو عوام وخواص کے دلوں پر حکومت کرتی رہی ہے۔ ملی جلی تہذیب کی یہ امین، اپنے چاہنے والوں کے ایک بڑے حلقے میں اچانک معتوب کیوں کر ہوئی؟ حیرانی کا سبب ہے۔ اپنے ہی جائے مسکن میں اس کی کسمپرسی کی یہ عبرت ناک داستان ضرور ہے مگر فن کاروں کا لہجہ حکیمانہ اور درویشانہ ہے جس کی زیریں لہریں یہ بھی تاثر دیتی ہیں کہ مادری، تہذیبی اور تمدنی زبان کو جس علاقے سے نکالا گیا ہے وہاں اب بھی کہیں کہیں اس کی جڑیں برقرار ہیں۔ نہ جانے کب رحمتوں کی بارش ہو، اُن میں جان پڑے، کونپلیں پھوٹیں، تروتازگی بحال ہو۔
تخلیقی فن پاروں سے ذرا ہٹ کر صحافتی اور تنقیدی مضامین اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر اردو زبان کے ساتھ ان دیکھی ہورہی ہے، جان بوجھ کر اسے روزی، روٹی سے دور رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ خالی آسامیاں بڑی مشکلوں سے بھری جارہی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن افسانوی ادب پاروں کی قرأت کے بعد قاری خود سے سوال کرتا ہے کہ اردو مخالفین نے اگر مختلف حربے اپنائے تو عاشقین نے اس کاتدارک کیا کیا؟ مان لیا تقسیم وطن کے عذاب کے وقت لب کشائی کی جرات نہیں تھی تو بعد میں کیالائحۂ عمل اختیار کیا گیا؟غیر افسانوی ادب اس جانب مہمیز کرے گا کہ ہم کیوں اِسے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رکھ سکے؟ دوسری قوموں کے تہذیبی اور لسانی عروج وزوال سے سبق کیوں نہیں لیا۔ یہودی آخر کیوں صدیوں کی جلاوطنی کے بعد بھی ’عبرانی‘ کو نہیں بھول سکے۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں کی زبان میں مہارت حاصل کی مگر بغیرکسی سرکاری یا نیم سرکاری سرپرستی کے عبرانی زبان کو زندہ رکھا اور اسرائیل کے وجود میں آتے ہی اُسے مذہبی نہیں، سرکاری زبان کادرجہ عطا کردیا۔ خود ہندوستان میں سنسکرت کے عاشقوں نے یہ نمونہ پیش کیاکہ مادری زبان کاروزی روٹی سے کم، عمل وجہد سے زیادہ تعلق ہے یا پھر اِس جانب توجہ مبذول کرائی جائے گی کہ دیکھو بنگالیوں اور پنجابیوں نے اپنی زبان سے محبت کا ایساثبوت دیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اِس کے برعکس کشمیری گفتار کے غازی بنے رہے اور آج یہ حال ہے کہ کشمیری میں کسی مالی تعاون کے بعد ایک آدھ اخبار ہی نکلتا ہے، جو رونق ہے وہ محض سرکاری سرپرستی کی بدولت۔ لیکن تخلیقی ادب براہِ راست کچوکے نہ لگا کر فن پاروں میں واقعات اور کرداروں کے عمل اور ان کے مکانی وزمانی ربط سے ایسا منظر نامہ پیش کرتا ہے کہ جس کے تانے بانے قاری خود بُنتا ہوا محاسبہ پر مجبور ہوتا ہے۔ اردو کے ایک ممتاز افسانہ نگار نے اپنی زبان کی تعمیر وتشکیل اور عوامی مقبولیت کو واضح کرنے کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا جو محاسبہ کے لیے نہایت موثر اور کارگر ثابت ہوا۔ وہ اُسے ایک حسین وجمیل محبوبہ کی شکل دیتا ہے جسے عدم توجہی، تغافل اور تعصب نے شدید گُھٹن میں مبتلا کردیا ہے۔ وہ اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے حبس کی وجہ سے تلملاتی ہے۔ تشخیص کھلی فضا قرار پاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر قاری خود بخود محسوس کرلیتا ہے۔ اِس طرح کے فن پارے آج کے بے حد تناؤ بھرے ماحول میں حقائق سے روشناس کرانے کے موثر اور کارگر طریقے ثابت ہوسکتے ہیں۔ ورنہ سامنے کی بات تو یہ ہوگی:
’’کولکاتا میں کئی سو سال سے چینی آباد ہیں۔ اُن کی مجموعی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ وہ آرام سے ہندوستانی (یعنی اردو) اور بنگالی بولتے ہیں لیکن اپنی زبان کو بھی کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چینی زبان میں کتابیں بھی چھاپتے ہیں اور اخبار بھی، اور خود اسے رضاکارانہ طور پر ہر چینی کے گھر پہنچاتے بھی ہیں ‘‘۔
موازنہ کے ساتھ ساتھ چُبھتا ہوا سوال بھی ہوگا کہ زندہ قوموں کاوطیرہ یہی ہوتاہے؟ شاید لکھنؤ اور دہلی دبستان کے بہی خواہ اِس سبق کو بھول گئے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر کام کرنا تو دُور کی بات اردو کاصاحبِ حیثیت حلقہ جن کی روزی، روٹی، عزت وشہرت کا تمام تر دارومدار ’اردو‘پر ہے وہ اخبار ورسائل کو خرید کر پڑھنے کی زحمت بھی کم ہی گوارا کرتے ہیں۔ کتابیں تو نذرانے کے طور پر ملتی ہیں جنھیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتاہے۔ اگر کبھی کبھار مدیر نے عاجزانہ طور پر رسالہ یا اخبار بھیج دیا تو صاحبِ ثروت شخص کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے اور ایسا لمحہ اُس کی عدیم الفرصتی کی بنا پر بہت کم میسر آتا ہے پھر جوش میں اِس جانب بھی نشان دہی کردی جاتی ہے کہ پرائمری اسکول سے یونیورسٹی کے قد آور اساتذہ تک محاوروں کے مختلف معنی بتاتے رہتے ہیں لیکن اردو کا طالب علم ’’جیسا راجہ ویسی پرجا‘‘ کے مفہوم کو نہ صرف بھانپ لیتا ہے بلکہ عملی طور پر اُس کے عمیق معنی بھی سمجھ لیتا ہے کیوں کہ عالم گیریت اور صارفیت کے اِس برق رفتار دور نے اُسے نقشِ پا کی پیروی کے عمل سے واقف کرادیا ہے۔
غیر تخلیقی ادب کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم۔ لیکن اس میں براہِ راست گفتگو کاانداز حاوی ہوتا ہے جو واضح کرتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بسے ہوئے اُس دور کو بیتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے جب سائنس، سوشل سائنس کے اساتذہ، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ اردوکی کتابیں، رسائل اور اخبار خریدتے تھے۔ قریوں اور محلوں میں ہی نہیں ریلوے اسٹیشن پر بھی اردو کے مختلف اخبارات ورسائل کے ساتھ تاریخی، رومانی جاسوسی ناول بہت کم قیمت پر بآسانی دست یاب تھے مگر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ لاکھ ٹونے ٹوٹکے کے باوجود وہ شادابی واپس نہیں آنے پارہی ہے۔ دوسرے شعبہ جات کے اردو دوست اب بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر ادبی مذاکروں میں شریک ہورہے ہیں، اپنی تخلیقات سے محفلوں کوگرمارہے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بچا ہوا ماحول بھی رُخصت نہ ہوجائے۔ ادیب دعویٰ اور دلیل کی بنیادوں پر سوال قائم کرتا ہے کہ اِس ابتر صورتِ حال کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اسباب تلاش کرتے ہیں مگر ہماری گُل افشانی اور فربہ ذہن کی حکمتِ عملی پہلے ہی سے جواز تلاش کرلیتی ہے۔ آخر مٹھی بھر محبانِ اردو ہماری اپنی بے حسی کے لیے کیاطریقۂ کار اختیارکریں، سمجھ سے باہر ہے۔
فکشن نگار یا شعراء حضرات اپنے ادب پاروں میں اسی ذہنی کشمکش اور استعجابی کیفیت کو پیش کرتے ہیں مثلاً ’’آخری سواریاں ‘‘ خلق کرتے ہوئے ناول نگار نے جو ماحول منعکس کیا ہے، اُس میں قاری نمناک فضا اور دل کو مسوس لینے والی صورت حال سے دوچار ہوتاہے، اور غیر محسوس طور پر اُس کے ذہن پر یہ نقش ہوجاتا ہے کہ اردو زبان جس نے معصومیت اور اُلفت کے نغمے بکھیرے، گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا، محبت ومساوات کو گلے لگایا، اُس سے چشم پوشی، بیزاری، نفرت اور تعصب کیوں؟ زبان کو دفنانا در اصل تہذیب کی موت ہے، اور تہذیب کے دفنانے کا نوحہ اتنا درد انگیز ہوتا ہے کہ چٹانیں بھی چٹخ جاتی ہیں۔
متذکرہ گفتگو کامقصد کسی کی دل شکنی نہیں بلکہ اس جانب اشارہ کرنا ہے کہ دونوں ہی قسم کی تحریریں دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر لکھی جارہی ہیں لیکن چند دہائیوں میں جوصورتِ حال پیدا ہوچکی ہے وہ بے حد نازک اور تشویش ناک ہے۔ ذرا سی بھی تلخی ناگواری میں اضافہ کرسکتی ہے تو کیوں نہ وہ اندازِ تخاطب اختیار کریں جو فضا کو موثر اور معطر بنائے۔ ایسے میں تخلیقی انداز کچھ زیادہ ہی کارگر ہوتا ہے حالاں کہ مقصد، منشا اور نصب العین دونوں کاایک ہے۔ بس طرزِ بیان مختلف اور پیش کش کا انداز جُداگانہ ہے تو پھر کیوں نہ اردو زبان کے کھوئے ہوئے مقام ومرتبہ کے حصول کی لگن میں وہ لہجہ اختیار کریں جس کے لیے اردو زبان جانی جاتی ہے، اور وہ انداز اپنائیں جو سبھی کے دلوں کو جیتتے ہوئے محاسبہ پر مجبور کرے ؎
نہیں ہے نا امید اقبالؔ اپنی کشت ویراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

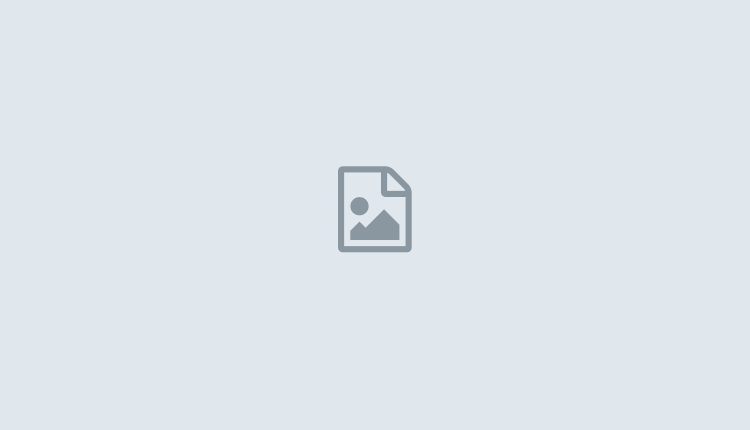
تبصرے بند ہیں۔